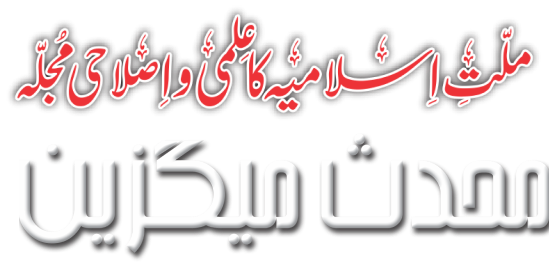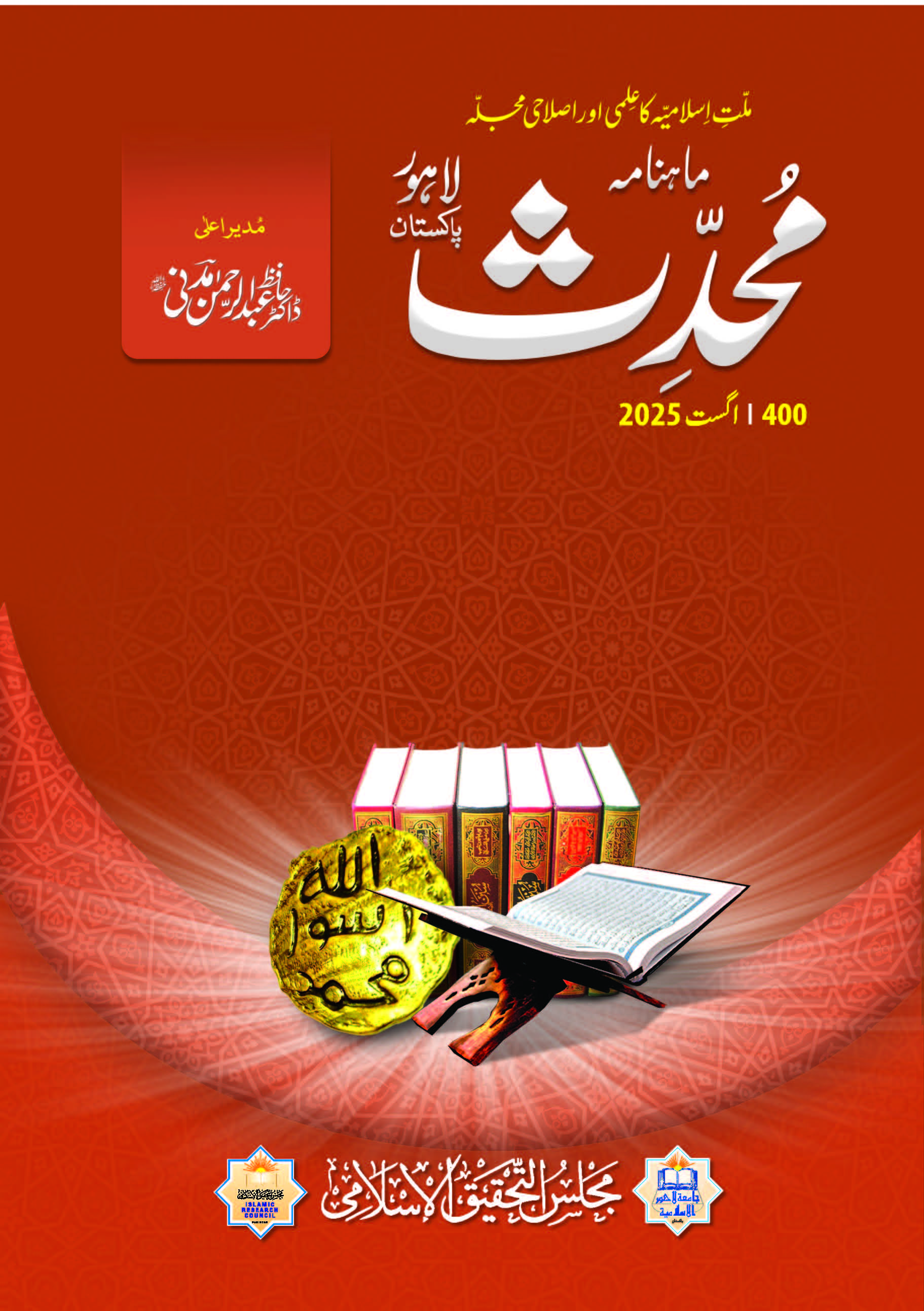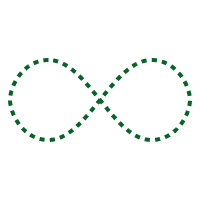مولانا اصلاحی کی تفسیر ’تدبر قرآن‘ میں
فکری تضادات وتناقضات
تفسیر ’’تدبر قرآن‘‘ کا ایک افسوس ناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سے واضح اور کھلے علمی وفکری تضادات (Contradictions)پائے جاتے ہیں جو کہ اس کے منصف کی کج اندیشی اور ذہنی الجھاؤ کی غمازی کرتے ہیں۔وہ کسی بات کا ایک جگہ اثبات واقرار کرتے ہیں تو دوسری جگہ اسی کی نفی اور انکار کر دیتے ہیں اور اس طرح ’’دروغ گو را حافظہ نباشد‘‘ کا مصداق ٹھہرتے ہیں۔ ذیل میں ان کے ایسے بکثرت تضادات وتناقضات میں سے کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ گویا ’’مشتے از خروارے‘‘
1۔کیا کوئی رسول کبھی قتل ہوا؟
’’تدبر قرآن‘‘میں کہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی رسول کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے اور کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نہ صرف یہ کہ قتل ہو سکتا ہے بلکہ فی الواقع قتل ہوا بھی ہے۔ اس کھلے تضاد کو دیکھنے کے لیے ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ کیجیئے:
پہلے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسولوں میں سے کسی کا قتل ہونا ثابت نہیں ہے۔
- چنانچہ سورہ آل عمران(3/55) کی تفسیر میں لکھا ہے:
’’رسولوں کی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ وہ ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ رسولوں میں سے کسی کا قتل ہونا ثابت نہیں[1]۔‘‘
- مزید سورہ قٓ (50/14)کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :
’’رسولوں میں سے کسی کا اس کی قوم کے ہاتھوں قتل ہونا ثابت نہیں ہے[2]۔‘‘
پھر دوسرے مقامات پر اس کے بالکل بر عکس یہ اقرار واعتراف کیا ہے کہ کسی رسول کا قتل ہونا نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ کئی رسولوں کو با لفعل قتل بھی کیا گیا ہے۔
- چنانچہ سورہ آل عمران (3/144) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :
’’پہلے یہ غلط فہمی دور فرمائی کہ محمدﷺ کوئی ما فوق بشر ہستی نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ جس طرح پہلے رسول گزر چکے ہیں اس طرح ایک دن ان کو بھی بہر حال وفات پانا ہے اور اس کا بھی امکان ہے کہ وہ شہید کر دیے جائیں لیکن اللہ کے دین کو ہمیشہ باقی رہنا ہے[3]۔‘‘
- مزید اسی مذکورہ آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ :
’’مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں بہت سے رسول گزرے ہیں اسی طرح محمدﷺ بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، جس طرح کی آزمائشیں دوسرے رسولوں کو پیش آئیں اسی طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں انہیں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ جس طرح تمام رسولوں کو موت کے مرحلہ سے گزرنا پڑا انہیں بھی ایک دن وفات پانا ہے۔ ان کے رسول ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ وفات نہیں پائیں گے یا قتل نہیں ہو سکتے[4]۔‘‘
- پھر سورہ آل عمران(3/183) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :
’’یہ عذر یہودیوں نے محض شرارت سے ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، گھڑا تھا۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر جواب دے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے ایسے رسول آ چکے ہیں جو نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا جس کا تم نے ذکر کیا تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تمہارا یہ فعل تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم اپنی اس بات میں بھی جھوٹے ہو۔ اگر تم کو یہ معجزہ دکھا بھی دیا جائے گا جب بھی تم اپنی اسی ضد پر اڑے رہو گے اور ایمان نہ لانے کا کوئی اور بہانہ تلاش کر لو گے[5]۔‘‘
- پھر سورہ المائدہ (5/70) کی تفسیر کرتے ہوئےلکھا ہے کہ :
’’اب یہ اس بات کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ کیوں ان اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دینی حیثیت نہیں ہے؟ فرمایا کہ ان سے جس کتاب وشریعت کی پابندی کا عہد لیا گیا تھا اور جس کی تجدید و یاددہانی کے لیے اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنے بہت سے رسول اور نبی بھی بھیجے، اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا اور جو رسول اس کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے آئے ان کی باتوں کو اپنی خواہشات کے خلاف پا کر یا تو ان کی تکذیب کر دی یا ان کو قتل کر دیا[6]۔‘‘
صاحب ’’تدبر قرآن‘‘ کے اس واضح اور کھلے فکری تضاد کو دیکھنے کے بعد اصل حقیقت کی طرف آئیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ امر قرآن کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ نبیوں کے علاوہ بعض رسولوں کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے لیے درج ذیل آیات دیکھ لیجیئے۔
- سورہ آل عمران میں دوسرے رسولوں کی طرح حضرت محمدﷺ کے لیے بھی وفات پانے یا قتل ہو جانے کی دونوں صورتوں کے امکان کا ذکر کیا گیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :
﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ١ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ﴾ ]آل عمران:3/144[
’’اور محمد(ﷺ)تو بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے اور جو کوئی بھی الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا۔‘‘
- سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ :
﴿اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ۰۰۸۷﴾
] البقرة:2/87[
’’تو کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے نفس کو پسند نہ آئی تو تم نے تکبر کی راہ اختیار کی۔ پھر بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے تھے۔‘‘
- سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ :
﴿لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَۗ۰۰۷۰﴾ ]المائدة :5/70[
’’بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کے پاس کئی رسول بھیجیے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لایا جو ان کو پسند نہ آئی تو بعض کو وہ جھٹلاتے اور بعض کو قتل کر ڈالتے تھے۔‘‘
- سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوا کہ :
﴿اَلَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ بِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ۠ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۱۸۳﴾
] آل عمران:3/183[
’’یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کرے جسے آگ کھا جائے۔ آپؐ کہہ دیجیئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے، نشانیاں لے کر اور اس چیز کے ساتھ جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم سچے ہو۔‘‘
اس مقام پر بنی اسرائیل کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ کسی ایسے رسول پر ایمان نہ لائیں جو ان کے سامنے نیاز یا قربانی کوآسمانی آگ سے نہ جلا دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا یہ جواب دیا ہے کہ اے نبیﷺ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہی بات ہے تو جو رسول اور پیغمبر ان کے پاس دلائل اور مذکورہ معجزہ بھی لاتے رہے، ان کی انہوں نے تکذیب کیوں کی تھی اور ان میں سے بعض کو قتل کیوں کیا تھا؟
قرآن مجید کی یہ واضح نصوص ہیں جن سے صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی بعض اوقات اپنی قوم کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ بالخصوص بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے بہت سے رسولوں کو نہ صرف جھٹلایا تھا بلکہ ان کو قتل کر بھی ڈالا تھا۔
2۔کیا ابلیس شیطان مر چکا ہے؟
صاحب ’’تدبر قرآن ‘‘ کے فکری تضادات میں ایک یہ تضاد بھی ہےکہ وہ کبھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ابلیس شیطان مر چکا ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ اور موجود ہے اور اسے قیامت تک کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنے وسوسوں اور فریب کاریوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا رہے۔ موصوف کے اس کھلے تضاد اور تناقص کو دیکھنے کے لیے ان کی کتاب کے درج ذیل مقامات ملاحظہ کیجیئے:
- انہوں نے سورہ البقرہ(2/34) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ :
’’شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ خدا کی نافرمانی کی روش اختیار کر لیتے ہیں وہ لوگ ابلیس کی ذریت اور اس کے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں[7]۔‘‘
- دوسری جگہ سورہ الناس(114) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :
’’شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے جو دلوں میں وسوسہ اندازی کا پیشہ اختیار کر لیں وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ جس شیطان نے بابا آدمؑ کو دھوکا دیا، قرآن میں تصریح ہے کہ جنوں میں سے تھاجو لوگ اس کو ایک مستقل مخلوق اور زندہ ہستی سمجھتے ہیں ان کا خیال غلط ہے۔[8]‘‘
ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ صاحب ’’تدبر قرآن‘‘ کی رائے میں ابلیس شیطان نہ تو کوئی مستقل مخلوق ہے اور نہ اب زندہ ہے بلکہ عرصہ ہوا وہ مر چکا ہے۔پھر اسی کتاب میں موصوف اس متفقہ اسلامی عقیدے کو بھی مانتے ہیں کہ ابلیس شیطان آج بھی زندہ موجود ہے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے اور انہیں بہکانے میں لگا ہوا ہے۔
- چنانچہ انہوں نے سورہ طٰہٰ (20/120) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :
’’ابلیس استکبار اور حکم خدا وندی کی نافرمانی کے باعث جنت سے راندہ ہو چکا ہے لیکن اس نے قیامت تک کے لیے آدمؑ اور اولاد آدمؑ پر اپنا چلتر آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت حاصل کر لی تھی[9]۔‘‘
- پھر سورہ صٓ (38/79۔81) کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ :
’’اللہ تعالیٰ کی اس لعنت سے ابلیس نے گمان کیا کہ شاید اس کی مہلت عمل ختم کی جا رہی ہے اور اس کو انسان کے خلاف زور آزمائی کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے درخواست کی کہ اس کو اس دن تک کے لیے مہلت دی جائے جس دن لوگ اپنے اعمال کے حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت دے دی[10] ۔‘‘
- پھر سورہ بنی اسرائیل (17/53) کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے:
’’اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، ہر وقت اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ کب کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ وسوسہ اندازی کرکے سارے کام کو خراب کر دے[11]۔‘‘
- پھر سورہ الزمر (39/31) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :
’’اس دنیا میں شیطان کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا کام بھی جاری ہے[12]۔‘‘
اس تفصیل سے صاحب ’’تدبر قرآن‘‘ کا یہ فکری تضاد کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کبھی تو ابلیس شیطان کو زندہ اور موجود مانتے ہیں اور کبھی اسے مردہ در گور قرار دے کر اس کی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
3۔ قرآن اور پانچ فرض نمازوں کے اوقات
’’تفسیر تدبر قرآن‘‘ میں ایک فکری تضاد یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں کبھی یہ کہا گیا ہےکہ قران میں پانچ وقت کی فرض نمازوں کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے اور اس کے لیے محض اشارات ملتے ہیں ۔مگر پھر اپنی اسی بات کی تردید کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ قران میں پانچ اوقات کی فرض نمازوں کا ذکر موجود ہے۔‘‘
- اپنی پہلی بات کے حق میں سورہ النساء(4/103) کی تفسیر میں مذکور ہے کہ :
’’ اس آیت سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اوقات کی پابندی اقامت صلوٰۃ کے شرائط میں سے ہے۔ دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ نبی ﷺ نے اہل ایمان پر جو کچھ فرض کیا ہے وہ عین اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ یہ بات اس طرح نکلتی ہے کہ نمازوں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ اوقات کے اہتمام کے ساتھ فرض ہیں ۔در آنحا لیکہ اوقات نماز تمام تر نبی ﷺ کے مقرر کردہ ہیں، قرآن میں ان کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اشارات ہیں[13]۔‘‘
- پھر اسی بات کی خود ہی تردید کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ (20/130) کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:
’’ اس آیت سے ان لوگوں کے خیال کی نہایت واضح طور پر تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔قرآن میں صرف فرض نمازوں ہی کی نہیں، بلکہ اشراق اور تہجد کے اوقات بھی مذکور ہیں۔ نبی ﷺ نے انہی اوقات کو اپنے عمل سے منضبط کر کے ان کی حد بندی فرما دی۔ مختلف نمازوں کی شکلیں بھی معین فرما دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کن نمازوں کی حیثیت فرض واجب کی ہے اور کن کی حیثیت نوافل کی۔ ظاہر ہے کہ ان تمام تفصیلات کا بتانا اور ہر نماز کی حدود و اطراف کا معین کرنا نبی ﷺ کا کام تھا اس لیے کہ آپ ﷺ صرف قرآن کے سنا دینے والے ہی نہیں بلکہ ان کے معلم بھی تھے[14]۔‘‘
- پھر سورہ بنی اسرائیل(17/78) کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ:
’’ اس سے معلوم ہوا کہ دن رات میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر خود قرآن میں ہے۔بلکہ آگے والی آیت سے معلوم ہوگا کہ تہجد اور اس کے وقت کا ذکر بھی کرقرآن میں ہے ۔اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں پانچ وقت کی نمازوں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ایسے
سر پھیرے لوگوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے[15]۔‘‘
یعنی پہلے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں اوقات نماز کی کوئی صراحت نہیں، محض اشارات ملتے ہیں اور پھر اپنے اس دعوے کی خود ہی تردید کر دی کہ دن رات میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے اور اس بات کا انکار صرف سر پھرے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔
جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
4۔فرقہ خوارج کی گواہی؟
یہ امر صاحب ’’تدبر قرآن‘‘ کے فکری تضادات میں سے ہے کہ انہوں نے سورۃ النور (24/2)کی تفسیر میں جہاں شادی شدہ زانی کے لیے حد رجم یعنی سنگساری کی سزا کا انکار کیا ہے، وہاں اپنے اس موقف کے حق میں اور اپنی تائید و حمایت میں خوارج کے گمراہ فرقے کو بطور شاہد عادل اور گواہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:
’’چنانچہ خوارج اس نسخ یا تخصیص کو نہیں مانتے ۔وہ رجم کا انکار کرتے ہیں اور اس حد کو، جو آیت میں مذکور ہے، ہر قسم کے زانیوں کے لیے عام مانتے ہیں[16]۔‘‘
حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی کتاب ’’مبادی تدبر القرآن‘‘ میں خوارج کے اس گروہ کو ایک فتنہ قرار دے چکے ہیں، انہوں نے لکھا :
’’ قرآن فتنوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا،فتنوں کو ابھارنے اور ان کوغذا دینے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی جتنے فتنے اٹھے یا اٹھ رہے ہیں وہ سب قرآن ہی کے آڑ میں نمودار ہوئے۔ خوارج اپنے گمان کے مطابق قرآن مجید ہی کے سہارے ابھرے، باطنیوں کی تمام استدلالات کی بنیاد ان کے خیال میں قرآن مجید ہی پر ہے،بابیوں اور بہائیوں نے جو کچھ کہا ،اپنے زعم کے مطابق قرآن ہی سے کہا، قادیانوں کی نبوت کی اساس، ان کے دعوے کے مطابق قرآن مجید ہی پر ہے اور چکڑا لوی تو قرآن کے سوا کچھ بھولتے ہی نہیں [17]۔‘‘
ہم سمجھتے ہیں کہ کسی گروہ کو پہلے فتنہ قرار دینا اور پھر اپنے کسی موقف اور بیانیے کے حق میں گواہ اور ’’شاہد عادل‘‘ بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے نظریات بھی خواج والے ہیں ، اور یقیناً ایسا ہی ہے ۔
5۔بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ کیسے بنا؟
تفسیر ’’تدبر قرآن‘‘ میں ایک فکری تضاد وتناقض یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ موسیٰکے عصا مارنے کے معجزے نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر سے راہ نکالی تھی لیکن پھر دوسری جگہ اس معجزے کا انکار کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ کام محص ایک پوربی ہوا کے تصرف کے نتیجے میں ہوا تھا۔ جس نے بنی اسرائیل کی خاطر سمندر کے اندر سے گزرنے کے لیے( مدو جزر پیدا کرکے)خشک راستہ بنا دیا تھا۔
پہلے انہوں نے موسیٰ کے عصا کا معجزہ بیان کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ (20/23) کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ :
’’خود قرآن میں عصا کے جو کرشمے مذکور ہیں ان کی عظمت ظاہر ہے۔ اسی عصا نے ان کے لیے سمندر سے راہ نکالی اور اسی سے انہوں نے ایک پہاڑی سے اکٹھے بارہ چشمے جاری کر لیے[18]۔‘‘
اس کے علاوہ اسی سورہ طٰہٰ (20/77) کے الفاظ : ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ ﴾ ( ان کے لیے دریا میں ایک خشک راہ کھول لو) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:
’’بحر سے مراد یہاں بحر احمر کی شمالی خلیج ہے۔ ہدایت ہوئی کہ پوری جماعت کے ساتھ ساحل سمندر پر پہنچو اور اپنی لٹھیا سمندر پر مار کر اس کے اندر سے لوگوں کے لیے خشک راہ پیدا کر لو۔
یہ اسلوب بیان ظاہر کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نےاپنے معجزے کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کو بخشا کہ تم اس کے اشارے سے سمندر کو حکم دو گے تو وہ تمہارے گزرنے کے لیے خشک راستہ نکال دے گا [19]۔‘‘
پھر اسی صفحے پر اسی آیت کی تفسیر میں تورات کا حوالہ دے کر اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہوئے لکھا ہے کہ :
’’ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ پوربی ہوا کے تصرف سے ظہور میں آیا۔ اس سے خلیج کا پانی اس طرح دو حصوں میں منقسم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے خشک راستہ پیدا ہو گیا[20]۔‘‘
اس طرح موسیٰ کے معجزہ عصا کے کرشمے کا انکار کرتے ہوئے اسے محض ایک مشرقی ہوا کا تصرف قرار دے دیا۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ محرف شدہ تورات کے بیان کی تصدیق کرکے قرآن کے فرمان کی تکذیب کر دی۔
6۔ لفظ ’’مدینون ‘‘ کے معنوں میں تضاد
تفسیر ’’تدبر قرآن‘‘ میں لفظ ’’مدینون‘‘(مدنیین) کے معنوں میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔
سورہ الصافات(37/53) میں مشرکین کا یہ قول حکایتہً بیان ہوا ہے کہ :
﴿ءَاِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ۰۰۵۳﴾
اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ:
’’کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم بدلہ پانے والے بنیں گے۔ ‘‘
مزید اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:
’’کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو اپنے اعمال کی جزا وسزا بھگتنے کے لیے دوبارہ اٹھا جائیں گے[21]۔‘‘
پھر سورہ الواقعہ( 56/86۔87) میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد :
﴿فَلَوْ لَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَۙ۰۰۸۶ تَرْجِعُوْنَهَاۤ۠ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۸۷﴾
اس کا ترجمہ یہ کیا ہے:
’’پس کیوں نہیں ،اگر تم غیر محکوم ہو، اس جان کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔‘‘
پھر اس کی تفسیر میں لکھا ہے :
’’فرمایا کہ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم کسی ایسے کے محکوم ومقہور نہیں جو تم کو پکڑ سکے اور سزا دے سکے تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے جس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمارا فرشتہ نکال لیتا ہے۔ ’’مدین‘‘کے معنی محکوم اور مقہور (Under control) کے ہیں[22]۔‘‘
اس جگہ صاحب ’’تدبر قرآن‘‘ کا تضاد دیکھ لیجیئے کہ پہلی جگہ سورہ الصافات میں ’’مدینون‘‘ کا ترجمہ ’’بدلہ پانے والے‘‘ اور اس کی تفسیر جزا وسزا پانے والوں سے کی گئی تو یہ ترجمہ اور تفسیر بالکل درست تھی مگر جب دوسری جگہ وہی لفظ ’’مدینین ‘‘ مجرور ہو کر استعمال ہوا تو اس کا پہلے سے مختلف ترجمہ ’’محکوم ومقہور‘‘ کر دیا اور اس سے یہ مراد لی کہ مخاطب عرب مشرکین یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے ’’محکوم ومقہور‘‘ (Under control)نہیں ہیں۔ حالانکہ عرب مشرکین کا یہ عقیدہ ہر گز نہیں تھا کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس نہیں ہے[23]، وہ تو آخرت میں جزا وسزا کے منکر تھے۔ جس کی تردید [سورہ الواقعہ 56/86 میں] یہ فرما کر کی گئی کہ تم لوگ ضرور ایک دن اپنے اعمال کی جزا وسزا پانے والے بنو گے۔
7۔﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ﴾کے معنیٰ میں تضاد
صاحب’’تدبر قرآن‘‘ کے تضادات میں سے ایک تضاد یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ ’’ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ‘‘ (اے لوگو) کے خطاب ِعام کو کبھی عام مانتے ہیں اور کبھی اس سے مخصوص مخاطبین مراد لے لیتے ہیں۔
﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا۰۰۱۷۴﴾]النساء4/174[
’’اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک حجت آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین اتار دیا ۔‘‘
اس کے مخاطبین کے بارے میں لکھا ہے کہ :
’’اس آیت کا خطاب عام ہے جس میں مسلمان، اہل کتاب اور اہل عرب سب آ گئے ہیں[24]۔‘‘
- پھر اس خطاب ِعام کو عرب تک محدود کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ۰۰۲۱﴾
] البقرة:2/21[
’’اے لوگو! بندگی کرو اپنے اس خداوند کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گرزے ہیں تا کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو۔‘‘
پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
’’ (اے لوگو!) سے خطاب اگرچہ عام ہے لیکن یہاں مخاطب جیسا کہ اوپر گزرا ، خاص طور پر مشرکین عرب ہیں[25]۔‘‘
- پھر اسے عربوں کی ایک شاخ بنی اسماعیل تک مزید محدود کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ :
’’اس مجموعہ کی ابتدائی آیات (21۔29) میں بنی اسماعیل کو نبی ﷺ کی دعوت قبول کرنے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے[26]۔‘‘
اس طرح صاحب تدبر قرآن کی یہ چا بک دستی ملاحظہ ہو کہ پہلے تو انہوں نے ﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (اے لوگو!) کے عام مخاطبین کو محض مشرکین عرب کے ساتھ مخصوص اور محدود کر دیا۔پھرکمال ہوشیاری سے ان مخاطبین کو مزید محدود ومخصوص کرکے صرف بنی اسماعیل کو اس خطاب کا مخاطب ٹھہرا دیا۔ یا للعجب!
اس طرح قرآن کی جو دعوت ساری انسانیت کے لیے تھی اسے پہلے مشرکین عرب تک اور پھر بنی اسماعیل تک محدود و مقصور کر دیا ۔
واضح ہے کہ مخاطبین کا یہ تغیر وتبدل در اصل نتیجہ ہے’’نظم قرآن‘‘یا’’نظام قرآن‘‘ کے اس خود ساختہ نظریے اور جعلی فلسفے کا جس کی روشنی میں یہ پوری تفسیر ’’تدبر قرآن‘‘ لکھی گئی ہے۔
[1] تدبر قرآن : 2/106
[2] تدبر قرآن : 7/542
[3] تدبر قرآن : 2/183
[4] تدبر قرآن : 2/185-186
[5] تدبر قرآن : 2/220-221
[6] تدبر قرآن : 2/566
[7] تدبر قرآن:1، ص165
[8] تدبر قرآن:9/677
[9] تدبر قرآن:5/98
[10] تدبر قرآن: 6/550
[11] تدبر قرآن:4/ 511
[12] تدبر قرآن:6/ 586
[13] تدبر قرآن:2 / 373
[14] تدبر قرآن:5/ 107
[15] تدبر قرآن:4/530
[16] تدبر قرآن: 5 /365
[17] مولانا امین احسن اصلاحی،’’مبادی تدبر قرآن‘‘، ص 20۔21 ، مطبوعہ1971ء لاہور
[18] تدبر قرآن: 5/36
[19] تدبر قرآن:5/ 71
[20] تدبر قرآن:5/ 71
[21] تدبر قرآن:6/ 459۔468
[22] تدبر قرآن:8/ 181۔186
[23] ملاحظہ فرمائیں : العنکبوت29/19۔20۔61، لقمان31/25
[24] تدبر قرآن: 2/ 438
[25] تدبر قرآن:1/136
[26] تدبر قرآن:1/145