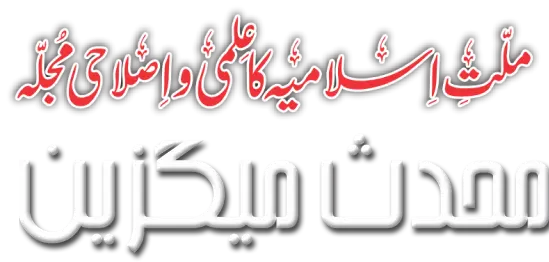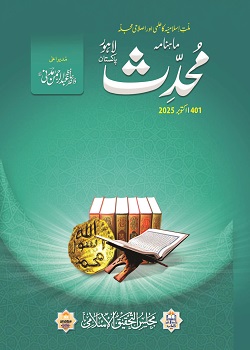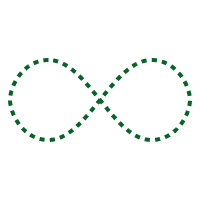محدث عبدالعزیز رحیم آبادیؒ اور ان کی تصنیف حُسن البیان
ماہ نامہ محدث میں ’’فکر و منہاج ‘‘کے عنوان سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کالم کے تحت سلفی منہاج بالخصوص برصغیر کی تحریکِ اہل حدیث کے بنیادی اور نمایندہ علمی لٹریچر پر تعارفی و تبصراتی مقالات شایع کیے جائیں گے۔ مقصود یہ ہے کہ اہلِ علم اور طلبہ کو تحریکِ اہل حدیث کی فکری میراث اور علمی ذخیرے سے رُوشناس کرایا جائے اور ان کتب کی اہمیت و امتیازات کو اجاگر کیا جائے۔اس سلسلے کا آغاز معروف تالیف ’’حسن البیان ‘‘پر مقالے سے کیا جا رہا ہے؛ آیندہ شماروں میں دیگر نمایندہ کتب پر بھی مقالات شایع ہوتے رہیں گے؛ ان شاء اللّٰہ (ادارہ) |
زیرِ نظر مقالہ دراصل محدثِ جلیل علامہ محمد عبدالعزیز رحیم آبادیؒ (م 1918ء) کی عظیم علمی تصنیف حسن البیان فی ما فی سیرۃ النعمان کے ہندستانی اڈیشن (جنوری 2022ء)کے لیے بہ طور ابتدائیہ لکھا گیا تھا۔ قبل ازیں 2021ء میں جب یہ کتاب محسنِ ملت محترم ڈاکٹر بہاء الدین ﷾ کی سعیِ جمیل سے پاکستان میں شایع ہو کر منظر عام پر آئی تو انھوں نے راقم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس پر اپنے تاثرات قلم بند کرے؛ یہ مقالہ اسی خواہش کی تعمیل میں سپردِ قرطاس ہوا اور بھارتی طباعت (ص 207 تا 220) میں شامل کیا گیا۔
اب نظرثانی اور معمولی حک و اضافے کے بعد اس مقالے کو افادۂ عام کے لیے ماہ نامہ محدث میں شایع کیا جا رہا ہے تاکہ نہ صرف کتاب کی علمی و تحقیقی اہمیت کا اندازہ ہو سکے بل کہ محدث رحیم آبادیؒ کی گراں قدر خدمات کا ایک اجمالی خاکا بھی سامنے آ جائے۔ (مقالہ نگار)
ـــــــــــــــــــــــــ
اہل اسلام کے مابین یہ امر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین کی بنیاد محض کتاب و سنت ہے کہ دین کی تکمیل رسول اللّٰہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہو چکی اور اب اس میں کسی شے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام کے بنیادی متون میں کتاب اللّٰہ یعنی قرآن کریم کی تحریر و ترتیب کا کام خود آں حضرت ﷺ کے عہد مبارک میں انجام پا گیا تھا؛ بعد ازاں اس کی جمع و تدوین حضرات صحابۂ کرامؓ کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچی۔ اسلامی شریعت کے دوسرے اساسی متن یعنی سنت رسول ﷺ کے بعض نوشتے بھی جناب نبی کریم ﷺ کی اجازت اور حکم سے معرضِ تحریر میں آئے لیکن اصل توجہ قرآن عزیز پر مرکوز ہونے کی بنا پر سنت کی تدوین و ترتیب کا کام موَخر رہا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سنت دراصل قرآنی احکام اور اوامر و نواہی کا عملی اظہاریہ تھا، چناں چہ اسے تعامل کی صورت میں محفوظ کیا گیا؛ اسی طرح پیغمبر گرامی ﷺ کے احوال و ارشادات کی حفاظت کے لیے عربوں کے یہاں حفظ و اتقان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو بھی بہ روے کار لایا گیا۔ پہلی صدی ہجری میں سنت کی کتابت پر بہ ہرحال زیادہ کاوش نہیں کی گئی کیوں کہ عربوں کو اپنے حافظے پر بہت ناز تھا اور لکھنے کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔
عہدِ تابعین میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ قرآن حکیم کے مانند اس کی تفسیر و تبیین یعنی سنتِ رسول ﷺ کو بھی دستاویزی شکل میں مدون کیا جائے؛ چناں چہ جناب عمر بن عبدالعزیزؒ (م 101ھ) کے ایما پر ائمۂ سنت نے اس کا بیڑا اٹھایا اور امام شعبی (م 109ھ)، امام ابن شہاب زہری (م 124ھ) اور قاضیِ مدینہ ابوبکر ابن حزم (م 120ھ) نے روایاتِ سنت کے مختلف مجموعے تیار کیے جنھیں اسلامی مملکت کے مختلف گوشوں میں پہنچا دیا گیا۔ ان بزرگوں کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا ہے اور اسی صدی میں امام دارالہجرۃ مالک بن انسؒ (م 179ھ) کا عظیم الشان ذخیرۂ حدیث مدون ہوا جسے آج موطا امام مالک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے متعلق امام کے تلمیذِ رشید امام شافعیؒ (م 204ھ) کا قول ہے کہ صفحۂ گیتی پر کتاب اللّٰہ کے بعد مالک کی کتاب سے بڑھ کر صحیح کتاب اور کوئی نہیں: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصحُّ من كتاب مالك. اس زمانے میں اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں جن میں جامع سفیان ثوریؒ قابل ذکر ہے۔
دواوینِ سنت کی جمع و ترتیب کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور تیسری صدی ہجری میں اپنےعروج و کمال کو پہنچا جس میں صحاح ستہ اور دیگر معروف کتب حدیث کی تدوین ہوئی۔ حدیث و سنت کی جمع و تدوین کا یہ سارا عمل جس مبارک جماعت کے ہاتھوں تکمیل پذیر ہوا، اسے اہل الحدیث اور طائفۂ محدثین سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کی مراد و منشا یعنی سنت نبوی کی نقل و روایت اور اسے کتابی صورت میں پیش کرنے کا یہ کارنامہ اس قدر مہتم بالشان ہے کہ امت کبھی اس احسانِ عظیم کے شکریے سے سبک دوش نہیں ہو سکتی۔ اب ہر شخص مذہب اسلام کے بنیادی متون کو بہ آسانی اپنے مطالعے میں لا سکتا اور اس چشمۂ ہدایت سے کسبِ فیض کر سکتا ہے۔
اہل الحدیث نے صرف متونِ کتاب و سنت کے ضبط و تدوین ہی پر اکتفا نہیں کیا بل کہ اس کے پہلو بہ پہلو اِن تحریری نوشتوں کی تفہیم و توضیح کا فریضہ بھی سرانجام دیا اور اس کے لیے وحیِ الٰہی کے اولین مخاطبین یعنی صحابۂ کرامؓ کے طرزِ فکر و عمل سے بھرپور استفادہ کیا۔ ان کا زاویۂ نگاہ یہ تھا کہ جس طرح قرآن و سنت کے الفاظ کی نقل و روایت کا سلسلہ بلا انقطاع جناب رسول اللّٰہ ﷺ تک پہنچتا ہے، اسی طرح ان کا فہم بھی اسی وقت معتبر ہو گا جب اس کی سند اُن نفوسِ قدسیہ سے ملے گی جو اِن کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔ زندگی میں پیش آمدہ نو بہ نومسائل کے حل و کشود کے لیے وہ فکر و اجتہاد کے بھی قائل تھے اور بہ وقتِ ضرورت اسے کام میں لاتے تھے؛ مگر اس باب میں وہ تکلف اور تصنع کو اچھا نہیں گردانتے تھے اور نہ فرضی مسائل وضع کر کے ظن و تخمین سے ان کا جواب تلاش کرنے ہی کو مستحسن سمجھتے تھے۔ اہل الحدیث کا مرکز چوں کہ حجاز رہا ہے جسے مہبطِ وحی کا درجہ حاصل ہے، اس لیے انھیں احادیث و آثار کے وسیع ذخیرے تک بہ سہولت رسائی حاصل تھی؛ چناں چہ ان کے یہاں دُور اَز کار عقلی توجیہات کا چلن رواج نہ پا سکا اور نہ اس کی نوبت ہی آئی۔
اس کے بالمقابل مرکزِ وحی سے دور دراز کے علاقوں میں جہاں آثار و سنن کے ذخائر اتنی کثیر تعداد میں دست یاب نہ تھے، بعض بزرگوں نے مسائلِ حیات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے اپنے مشایخ کے اقوال و فتاویٰ پر بناے استنباط رکھی اور قیاس و استحسان سے نسبتاً زیادہ استناد کیا۔ اس طریقِ استدلال کو اپنانے والا دبستان اہل الرائے کے نام سے معروف ہوا۔ اہل الحدیث کی علمی روایت میں اصحابِ پیغمبرؑ کے بعد امام سعید بن مسیب (م 94ھ)، امام مالک (م 179ھ)، امام شافعی (م 204ھ)، امام احمد (م 241ھ) اور ائمۂ حدیث و اصحابِ سنن کے اسماے گرامی نمایاں ہیں جب کہ دوسرے مکتبِ خیال کی سرکردہ شخصیات میں جناب ابراہیم نخعی (م 96ھ)، حماد بن ابی سلیمان (م 121ھ)، امام اعظم ابوحنیفہ (م 150ھ)، امام ابویوسف (م 182ھ) اور امام محمد شیبانی (م 189ھ) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔
ابتدائی ادوار میں یہ ایک علمی اختلاف تھا جس کی بنیاد بہ ہر حال طریق اجتہاد تھی کہ ہر دو فریق تقلید کے بجاے علمی استدلال اور اجتہاد کے علم بردار تھے؛ اگرچہ ان کے اسالیبِ استنباط میں اختلاف پایا جاتا تھا اور تعصب سے دامن بچاتے ہوئے منصفانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ ان میں سے اہل الحدیث کا اندازِ فکر اور طریقِ اجتہاد کتاب و سنت اور صحابۂ کرامؓ سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے؛ چناں چہ غیر جانب دار محققین نے اس کا کھلم کھلا اعتراف کیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال حجۃ الہند شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلویؒ (م 1762ء) ہیں جنھوں نے اپنی شاہ کار تصنیف حجۃ اللّٰہ البالغہ اور دیگر کتابوں میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ دوسرے بزرگوں کے طرزِ استنباط کی بنیاد بھی خدانخواستہ حدیث و سنت سے کسی نفور یا بے زاری پر استوار نہ تھی بل کہ روایات و آثار کی عدم دست یابی ان کی راہ میں حائل تھی۔
ان دونوں مکاتبِ فکر میں اختلافات کے باوصف باہم استفادے کی راہیں کبھی مسدود ہوئیں اور نہ اس میں کوئی عار ہی محسوس کی گئی؛ چناں چہ تاریخ کے اوراق میں یہ حقائق بہ تمام و کمال موجود ہیں کہ اہل الرائے کے نمایاں عالم امام محمد شیبانیؒ نے اس وقت کے اہل الحدیث کے سرخیل امام مالکؒ (م 179ھ) سے اکتسابِ علم کیا اور جماعت محدثین کے مایۂ ناز رکن امام محمد بن ادریس شافعیؒ (م 204ھ) نے امام محمد شیبانیؒ (م 189ھ) کے سامنے زانوے تلمذ تہہ کیے۔ ایک دوسرے کے علوم و افکار سے اخذ و استفادے کے اس قابل رشک تفاعل سے ہر دو مدارس پر بڑے اہم اور مفید اثرات مرتب ہوئے اور جہاں اہل الرائے میں حدیث و اثر سے اشتغال بڑھا، وہیں اہل الحدیث میں تعقلاتی اندازِ فکر کو فروغ ہوا جیسا کہ ان دونوں ائمہ کی علمی نگارشات سے عیاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علمی مکالمے کی قابل رشک روایت بھی انھی ائمہ کے ہاتھوں پروان چڑھی جیسا کہ امام محمدؒ کی الحجة علیٰ اهل المدینة اور ان کے ساتھ امام شافعیؒ کے فکری مناقشے اس پر شاہد عدل ہیں۔
خیرالقرون کے بعد جب بہ وجوہ تقلید شخصی کو فروغ ہوا اور بابِ اجتہاد کو مقفل کر کے اس کی کنجی کسی اندھے کنویں میں پھینک دی گئی تو بھی محدثین کے طائفۂ منصورہ نے منصوص مسائل میں اتباعِ سنت کی دعوت اور پیش آمدہ جدید معاملات میں اجتہاد و استنباط کے سلسلے کو جاری رکھا؛ چناں چہ تقلید و جمود کے مقابلے میں تجدید و اجتہاد کا عمل پورے تسلسل کے ساتھ جاری رہا جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اربابِ تقلید نے اجتہاد و استدلال کے اس سلسلے کو بڑا ناپسند کیا اور داعیان کتاب و سنت کے خلاف زبانی و تحریری فتوے صادر کرنے کے ساتھ ساتھ اہل اقتدار کو برانگیختہ کر کے انھیں قید و بند اور تشدد کی صعوبتوں سے دوچار کرنے کا بھی بھر پور اہتمام کیا جیسا کہ مکتب اہل الحدیث کے ایک نمایاں ترجمان اورمجدد امام ابن تیمیہؒ (م 728ھ) کے ساتھ ان کا سلوک تاریخ کے دفاتر کا حصہ ہے۔ کتاب و سنت کی بے آمیز دعوت اورصحابہ و سلف صالحین کے طریق و منہاج کی پیروی کے پرچار کے سوا آخر ان کا جرم کیا تھا؟!
اہل الحدیث کے خلاف اہل تقلید کی چیرہ دستیوں کی داستان بڑی الم ناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی جسے دہرانا یہاں منظور نہیں؛ اس لیے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہاں برصغیر پاک و ہند میں اس تاریخی فکری کش مکش کی جانب سرسری اشارا کیا جاتا ہے۔ مورخین کے بیانات سے یہ حقیقت مسلم ہو چکی ہے کہ ارضِ ہند میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی یہاں اہل الحدیث کا مذہب رائج ہوا اور اس سرزمین کے اکثر باشندے اسی مسلک پر کاربند رہے۔ بعد ازاں مختلف سیاسی اور سماجی عوامل کی کارفرمائی سے یہاں تقلیدی فکر کا رواج ہوا اور سرکاری سرپرستی کی وجہ سے حنفی مذہب کا غلبہ ہو گیا لیکن وقتاً فوقتاً اصلاح و تجدید کی صدائیں بلند ہوتی رہیں جن سے تقلید کے بجاے اتباع سنت کے جذبات فروغ پاتے اور متعصبانہ رویوں کی بیخ کنی ہوتی۔ ان مصلحین میں سب سے نمایاں کارنامے حجۃ الہند شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلویؒ (م 1762ء) نے سرانجام دیے جن کے مساعی جمیلہ سے تقلیدی جمود ٹوٹا اور کتاب و سنت سے راست استفادے کا ذوق پروان چڑھا۔ امام شاہ ولی اللّٰہ کی ان غیر معمولی علمی و اصلاحی کاوشوں کا شان دار تذکرہ محدث اسماعیل سلفیؒ کی کتابِ مستطاب تحریک آزادیِ فکر اور شاہ ولی اللّٰہ کی تجدیدی مساعی میں ملے گا۔ شاہ صاحب کا اسلوبِ فکر مقلدانہ نہیں بل کہ مجتہدانہ تھا؛ چناں چہ وہ حنفی خانوادے سے تعلق رکھنے کے باوجود تقلید کے اس جامد تصور کے مخالف تھے جو اس زمانے میں رائج تھا۔ انھوں نے تقلید کے مسئلے پر بڑی تفصیل اور وضاحت سے لکھا ہے اور اس کی علمی تنقیح کی ہے۔ خود اپنی وصیت میں انھوں نے طریق محدثین کی پیروی کی تلقین کی ہے۔ شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلویؒ کی اس تحریک کو ان کے پوتے مجدد شاہ اسماعیل شہیدؒ (م 1831ء) نے اوجِ کمال تک پہنچایا اور سنت پر علانیہ عمل کو فروغ دیا جس سے تحریک عمل بالحدیث کو بڑی تقویت ملی۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے خاندان ہی سے یہ فکر امام سید محمد نذیر حسین محدث دہلویؒ (م 1902ء) کو منتقل ہوئی جنھیں حجاز جاتے ہوئے شاہ محمد اسحاق محدث دہلویؒ (م 1845ء) نے اپنی مسند کا وارث بنایا۔ سید محمد نذیر حسین محدث دہلویؒ کے تلامذہ اور متوسلین کی علمی اور دعوتی کاوشوں سے اجتہاد اورعمل بالحدیث کی اس تحریک کو بے پناہ عروج نصیب ہوا جس کے اثرات آج تک نمایاں ہیں۔ اس سے جامد روایت پرستی پر ضرب لگی اور فقہی جمود ٹوٹا؛ اتباع سنت کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا؛ اور دلیل و برہان سے استناد و استدلال کو فروغ حاصل ہوا۔
اصحابِ تقلید کی جانب سےاس تحریک کی مخالفت بڑی شد و مد سے کی گئی۔ فتوے بازی کا بازار گرم ہوا اور حرمین شریفین کی سرزمین تک ان کی گونج سنائی دی۔ عاملین بالحدیث کو بد مذہب قرار دے کر انھیں مساجد میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے فتاویٰ صادر کیے گئے۔ موقع ملا تو مار دھاڑ اور جبر و تشدد سے بھی گریز نہ کیا گیا۔
علمی اعتبار سے اگرچہ قدیم اہل الرائے کاموقف بھی کم زور ہی تھا تاہم متاخرین مقلدین نے کوشش کی کہ تحریک عمل بالحدیث کا زور توڑنے کے لیے علمی استدلال بہ روے کار لایا جائے؛ چناں چہ اس ضمن میں دو باتیں بڑے زور و شور سے کی گئیں:
ایک یہ کہ اہل الحدث کا لقب صرف ان لوگوں کے لیے زیبا ہے جو حدیث کی نقل و روایت میں مشغول رہے اور انھی کو محدثین کہا جاتا ہے۔ آج کے لوگ چوں کہ نقل و روایت نہیں کرتے، اس لیے یہ اس لقب کے مستحق نہیں ہیں۔
دوسری بات اگلوں سے لی گئی کہ محدثین کا کام صرف احادیث کے الفاظ و اسناد کی روایت تک محدود تھا؛ ان کے معنی و مفہوم کی توضیح اور ان سے استنباط و استدلال کی ان میں صلاحیت تھی، نہ انھوں نے یہ کام کیا؛ اخذ و استنباط کا یہ عمل فقہا نے سرانجام دیا اور اصلی فقہا وہی تھے جنھیں اہل الرائے کا نام دیا گیا۔
یہ دونوں باتیں بالکل بودی ہیں کیوں کہ اہل الحدیث کے اطلاق کو صرف روایت کنندگان تک محدود کرنا درست نہیں ہے بل کہ ہر وہ شخص جو حدیث و آثار کو اعتقاد و عمل کی اساس سمجھتا اور انھیں ہر طرح کی راے، ذوق اور وجدان پر فوقیت دیتا ہے، اہل الحدیث میں شامل ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے:
ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً واتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن؛ وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث، والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما.[1]
’’ہم اہل الحدیث سے محض وہی لوگ مراد نہیں لیتے جو اس کے سماع، کتابت اور روایت پر اکتفا کرتے ہوں بل کہ ہماری نگاہ میں اس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے حدیث کے حفظ و معرفت اور فہم کا اہتمام کرتا اور ظاہر و باطن سے اس کا اتباع کرتا ہے۔ اہل القرآن کے لقب کا بھی یہی معنیٰ ہے۔ ان لوگوں کی کم از کم صفت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے محبت رکھتے اور ان کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں۔ پھر ان کے معنی و مقصود کی طلب و لگن میں لگے رہتے ہیں اور جب علم ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتے ہیں۔‘‘
جہاں تک دوسرا دعویٰ ہے کہ حدیث کے معانی اور مفاہیم کی گرہ کشائی محدثین کا وظیفہ نہیں اور یہ صلاحیت صرف فقہا ہی کوودیعت ہوئی ہے تو یہ چند در چند مغالطوں کا مجموعہ ہے:
ایک یہ کہ فقہا کا عنوان صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے جو محدثین کی صفوں میں نہ تھے بل کہ صرف ایک مخصوص مکتبِ خیال سے وابستہ تھے؛ حالاں کہ یہ خلافِ واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محدثین میں جہاں محض نقل و روایت کے ماہرین تھے، وہیں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جو اسناد و رجال سے روایت کے ساتھ ساتھ الفاظ و متون کی گہرائیوں میں اتر کر ان کے مطالب تک رسائی پاتے اور ان سے مسائل و نکات اخذ کرتے تھے؛ چناں چہ مالک و شافعی ہوں یا احمد بن حنبل اورمحمد بن اسماعیل بخاری، یہ نہ صرف اپنے زمانے کے محدثین کے امام تھے بل کہ فقہ و اجتہاد میں بھی سیادت اور پیشوائی کا منصب رکھتے تھے۔ ان حضرات کی کتابیں احادیث و آثار اور فقہی استدلال و استنباط کا حسین امتزاج ہیں، جب کہ دوسرے مدرسۂ فکر کے یہاں نصوص کی قلت نمایاں تھی جیسا کہ ابتدا میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔
یہاں ایک اور اہم حقیقت کا بیان بھی مناسب رہے گا اور وہ یہ کہ فقہ و اجتہاد کے اصول و ضوابط کو سب سے پہلے مدون کرنے کا سہرا بھی اہل الحدیث کے سر ہے کہ اسلامی تاریخ میں اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب کا اعزاز امام شافعیؒ کے الرسالہ کو حاصل ہے۔ اس کا اعتراف چند ایک متعصب احناف کے سوا سبھی نے کیا؛ چناں چہ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم (م 1956ء) نے اپنے رسالے تدوین فقہ و اصول فقہ میں ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اصول فقہ کی اولین تدوین کو حنفی ائمہ کا کارنامہ بتلاتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہے کہ بالاتفاق تمام موَرخین اور علما اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ فن اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب امام شافعی کا الرسالہ ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلویؒ کا ایک اقتباس نقل کر کے لکھتے ہیں:
’’جس سے صرف یہی معلوم نہیں ہوا کہ اصول فقہ کی تدوین کا کام سب سے پہلے امام شافعیؒ نے انجام دیا بل کہ یہ کہ امام شافعیؒ کی اس کتاب سے پہلے اس فن کے قواعد سرے سے منضبط ہی نہ تھے[2]۔‘‘
اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جون پوریؒ (م 2017ء) فرماتے ہیں:
’’اصول کے تو امام شافعی موجد ہیں اور اس میں سب کے امام ہیں۔ حنفیہ زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے سب سے پہلے اصول میں لکھا۔ وہ چند سطریں ہوں گی مگر امام شافعی کی پوری کتاب ہے، الرسالة؛ جو اصول فقہ اور اصول حدیث کی بنیاد اور سب سے پہلی کتاب ہے[3]۔‘‘
اصول فقہ کا اہم ترین مقصود ہی الفاظ و متون کی دلالتوں کو سمجھنا اور منشاے کلام تک رسائی پانا ہے۔ جب اس فن کے بانی ہی اہل الحدیث ہیں تو انھیں احادیث کے معانی اور مطالب سے نا آشنا قرار دینا کیوں کر قرین انصاف ہو سکتا ہے؟! یہ الزام صرف تعصب اور تنگ نظری کا شاخسانہ ہے؛ اس میں صداقت کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہے۔
برصغیر میں تحریک عمل بالحدیث کی مقبولیت کو دیکھ کر یہاں کے مقلدین اہل الرائے میں یہ احساس بھی بڑی شدت سے پیدا ہوا کہ ان کے یہاں حدیث و اثر کے مجموعوں کی بھی قلت ہے اور احادیث و سنن کے دفاتر تو درحقیقت مخالفین کے مدون کردہ ہیں اور اس لیے ان کے مذہب کو تقویت پہنچاتے ہیں؛ حالاں کہ ان احادیث کی جمع و تدوین سے کسی خاص راے کو تقویت پہنچانا یا اس کی برتری ثابت کرنا ہر گز محدثین کا مقصود نہ تھا؛ وہ تو حدیث و سنت کو ہر راے اور اجتہاد پر حَکم سمجھتے تھے اور ثابت شدہ احادیث کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے کو تقاضاے ایمان گردانتے تھے۔ بہ ہر حال یہاں نئے سرے سے حدیث کے مجموعے مرتب کیے گئے اور انھیں داخل نصاب کیا گیا تاکہ اپنے خاص فقہی مسلک کی ترجیح ثابت کی جا سکے؛ اگرچہ اس کے مطلوبہ اثرات بھی کم ہی مرتب ہو سکے اور ائمۂ محدثین کے مقابل ایسی کاوشوں کو پذیرائی نصیب نہ ہوئی۔
عاملین بالحدیث کی جانب سے کتاب و سنت کی دعوت کے لیے تعلیم و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ سمیت تمام وسائل کام میں لائے گئے۔ اس طرح ہزاروں علما تیار ہوئے اور بڑی مقدار میں علمی اور دعوتی لٹریچر شایع کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اربابِ تقلید کی تنقیدوں اور نکتہ چینیوں کا علمی اور مسکت جواب بھی دیا گیا۔ زیرِ نظر کتاب حسن البیان فی ما فی سیرۃ النعمان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کا مختصر پس منظر ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔
تحریک عمل بالحدیث کی مخالفت میں بہت سے حضرات نے حصہ لیا اور تقلیدی فکر کے غلبے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی۔ انھی افراد میں ایک علامہ شبلی نعمانیؒ (م 1914ء) بھی تھے جو اوائلِ عمر میں بڑی پختگی کے ساتھ حنفیت اور تقلید کے دامن سے وابستہ تھے۔ اسی زمانے میں امام اعظم کے اسم گرامی نعمان بن ثابتؒ کی نسبت سے نعمانی کا لاحقہ لگایا اور مختلف امتیازی مسائل پر مناظرانہ رنگ میں متعدد رسالے لکھے۔ تحریر و نگارش کے ساتھ ساتھ وہ دُو بدو مناظروں کے لیے بھی مستعد رہتے اور جہاں کسی عامل بالحدیث کا پتا چلتا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس سے مجادلے کے لیے چل پڑتے۔ عربیت اور فنون آلیہ میں پوری دست گاہ رکھتے تھے؛ ذہانت بھی وافر عطا ہوئی تھی؛ چناں چہ علی گڑھ کالج میں گئے اور سرسید کی تحریک میں شامل ہوئے تو عام فقہی مسائل سے ہٹ کر تاریخ و سوانح کو اپنا میدان بنایا۔ اسی سلسلے میں امام اعظم کے احوالِ زیست اور علمی کارناموں پر’’ سیرۃ النعمان ‘‘کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اس میں جہاں طریق نگارش کی لطافتیں قلب و ذہن کو تسکین پہنچاتی ہیں اور امام اعظم کی حیات و خدمات سے شناسائی ہوتی ہے، وہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات میں علمی استدال کی پاس داری نہیں ہو سکی اور عقیدت یا تعصب کے جذبات غالب آ گئے ہیں۔ مصنف نے اپنے ممدوح کی عظمت کے اثبات کی خاطر مکتبِ محدثین پر نقد و اعتراض کی راہ اپنائی حالاں کہ اس کی چنداں ضرورت نہ تھی۔
علی گڑھ تحریک کے بانی سرسید مرحوم نیچریت کے علم بردار تھے جو عقلیت پسندی کی زائیدہ تھی۔ شبلی اگرچہ اس نیچریت کے قائل نہ تھے تاہم ان پر عقلیت پسندانہ منہاج فکر کے اثرات ضرور مرتب ہوئے؛ ’’سیرۃ النعمان‘‘ میں محدثین اور علم حدیث پر ان کے تنقیدی ریمارکس سے یہ حقیقت بالکل واضح طور سے سامنے آتی ہے۔
یہ کتاب چھپ کر آئی تو مدرسۂ حدیث و اثر کی جانب سے ’’ حسن البیان فی ما فی سیرۃ النعمان ‘‘کے عنوان سے اس کے بعض مندرجات پر نقد سامنے آیا جو محدث عبدالعزیز رحیم آبادیؒ (م 1918ء) کی جنبشِ قلم کا نتیجہ تھا۔ مصنفِ علام، شیخ الکل فی الکل سید محمد نذیر حسین محدث دہلویؒ کے نمایاں تلامذہ میں تھے۔ ان کی ذاتِ والا صفات متنوع خوبیوں اور گوناگوں صلاحیتوں کا مرقع تھی۔ مبداے فیض کی کرم گستری سے انھیں علم و عمل کی فراونیاں میسر تھیں۔ قدرت کا عام دستور یہ ہے کہ ایک شخص علم و فن کے کسی ایک میدان یا زندگی کے کسی ایک ہی گوشے میں مہارت و اختصاص کا حامل ہوتا ہے اور دوسرے شعبوں سے اسے کچھ خاص واقفیت نہیں ہوتی؛ اگر وہ تعلیم و تدریس میں یکتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تصنیف و تالیف کے ذوق سے بھی بہرہ مند ہو؛ اسی طرح اگر وہ مبلغ اور خطیب ہے تو اس کا امکان بہت ہی کم ہے کہ وہ تحقیق و تدقیق میں بھی دست رس رکھتا ہو؛ اگر کسی کو تربیت اور تلقین کا ملکہ حاصل ہے تو یہ مشکل ہے کہ وہ جہادی کش مکش میں بھی شریک ہو سکے؛ ایسے ہی علم و ارشاد کا مسند نشیں شاید ہی کبھی جماعتی اور تنظیمی معاملات میں سرگرم کردار ادا کر سکے۔ لیکن ہمیں اس وقت حیرت و استعجاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جب ہم مصنف علام کے حالاتِ زندگانی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک بلند پایہ قلم کار تھے بل کہ درسیات اور علوم کتاب و سنت کے ایک ماہر اور کام یاب معلم بھی تھے؛ اسی طرح وعظ و ارشاد میں بھی ان کا اپنا ایک خاص اسلوب تھا اور ان کے موثر خطابات سے عالم اور عامی سبھی ایمان و عمل کی تازگی پاتے تھے۔ انھیں فن مناظرہ میں بھی مہارت حاصل تھی اور وہ دلیل و برہان اور حاضر جوابی سے مخالف کے موقف کی کم زوری واضح کر دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تنظیمی اور تحریکی مزاج بھی رکھتے تھے؛ وہ اپنے زمانے کی جہادی تحریک کی بھرپور تائید و حمایت کرتے اور انھیں مالی معاونت فراہم کیا کرتے تھے۔ وہ برصغیر کے عاملین بالحدیث کو منظم کرنے کے لیے بھی سرگرمِ کار رہتے اور اس مقصد کے لیےطویل سفر کیا کرتے تھے۔
’’حسن البیان‘‘ مصنف علام کے رشحاتِ فکر کا اظہاریہ ہے۔ اس میں علامہ شبلی نعمانیؒ کے بعض دعاوی کا ناقدانہ جائزہ لیا گیا ہے جن میں طائفۂ محدثین پر وہی الزامات ایک جدید اسلوب میں لگائے گئے ہیں جن کا اجمالی تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ایسی آ گئی ہیں جن کا علمی تجزیہ اس زیر نظر کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مسائل میں ایمان میں کمی بیشی کا مسئلہ، فقہِ اہل حدیث اور فقہ اہل الرائے، محدثین کی قوتِ فقہ و استنباط، اصول درایت اور خبر واحد سے زیادت علی الکتاب کی بحث خصوصاً لائق تذکرہ ہیں۔
محدث عبدالعزیز رحیم آبادیؒ نے محکم دلائل سے ثابت کیا ہے کہ شبلی نعمانیؒ کا نقطۂ نظر ان مباحث میں قرین صحت نہیں ہے بل کہ راہِ صواب سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمارے خیال میں اکثر مسائل تو وہ ہیں جو قدیم زمانے سے اہل الحدیث اور اہل الرائے یا اربابِ تقلید میں مختلف فیہ چلے آ رہے ہیں تاہم درایت کا مسئلہ ایسا ہے جسے شبلی نعمانی نے برصغیر میں اجاگر کیا اور اس کے بڑے دُور رس اثرات مرتب ہوئے۔ خود انھوں نے اپنی آخری (نا تمام) تصنیف ’’سیرۃ النبیؐ ‘‘میں بھی ان کا اطلاق و انطباق کرنے کی کوشش کی جن پر نہ صرف یہ کہ مکتبِ محدثین نے نقد کیا بل کہ احناف کے روایتی حلقوں کی طرف سے بھی ان کی تردید کی گئی۔ اس ضمن میں مولانا عبدالرؤف داناپوریؒ کی ’’اصح السیر ‘‘اور مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی ’’سیرۃ المصطفیٰ ‘‘کو دیکھا جا سکتا ہے۔
علامہ شبلی نعمانیؒ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ محدثین صرف روایت کرنا جانتے تھے اور درایت سے انھیں سروکار نہ تھا؛ درایت کے اصول امام ابوحنیفہؒ نے قائم کیے۔
یہ تاثر قطعاً نادرست ہے کیوں کہ فن حدیث کی کتب میں اس کا ذکر موجود ہے اور محدثین نے اس کو عملاً برتا ہے۔ امام صاحب سے ایسے کوئی اصول مروی نہیں ہیں، البتہ متاخرین کی موشگافیوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس بحث میں اصل نکتہ درایت کے معنی و مفہوم کی تعیین کا ہے۔ ماہرین فن کے یہاں درایت کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے سند و متن کے احوال سے واقفیت حاصل کی جائے۔ علامہ ابن الاکفانیؒ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ علم حدیث میں درایت سے مقصود وہ علم ہے جس سے روایت کی حقیقت، اس کے شرائط، انواع، احکام، راویوں کے احوال و شروط، مرویات کے اصناف اور ان سے متعلقہ امور کی پہچان ہوتی ہے:
وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها، وأنواعها،وأحكامها،وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها.[4]
علامہ عزالدین ابن جماعۃؒ (م 767ھ) کے بہ قول علم درایتِ حدیث سے ان قوانین کا علم مراد ہے جن سے سند و متن کے احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے:
علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.[5]
حافظ سیوطیؒ (م 911ھ) اور علامہ طاہر الجزائریؒ (م 1920ء) سے بھی اسی مفہوم کی تعریفیں منقول ہیں۔ طاش کبریٰ زادہ (م 968ھ) نے اس علم کو متن حدیث کے ساتھ خاص کیا ہے؛ ان کا کہنا ہے کہ علم درایت حدیث الفاظ حدیث سے سمجھے گئے معنی و مفہوم سے بحث کرتا ہے جس کی بنیاد قواعدِ عربیت، ضوابطِ شریعت اور نبی کریم ﷺ کے احوال سے مطابقت پر استوار پذیر ہے:
وإلى العلم بدراية الحديث، وهو علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد منها مبنياً على قواعد العربية، وضوابط الشريعة، ومطابقاً لأحوال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم[6] .
اسی تعریف کو لفظ بہ لفظ حاجی خلیفہ (م 1068ھ) نے اپنی کتاب کشف الظنون میں نقل کیا ہے۔ محدث محمد عبدالرحمان مبارک پوریؒ نے بھی یہ تعریفیں تحفة الأحوذی کے مقدمے میں درج کی ہیں۔ غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ محدثین نے ان تمام امور کا خیال رکھا ہے اوراحادیث کے اسناد و متون کی پوری پوری تحقیق کے ساتھ ساتھ ان کے فہم و استنباط پر بھی کامل توجہ دی ہے۔
علامہ شبلی نعمانیؒ نے اس کے بجاے ایک نئی تعریف وضع کی جس میں طبیعت، انسانی اقتضا اور عقلی قرائن کی روشنی میں روایات کو پرکھنے پر زور دیا۔ صاحبِ ’’حسن البیان ‘‘نے اس مبحث کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس سے علامہ شبلی کا مقدمہ پورے طور سے ختم ہو جاتا ہے۔ انھوں نے درایت کے تمام اصولوں پر الگ الگ بحث کر کے ان کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔
شبلی مرحوم کا درایت پر زور دینا ایک تو علی گڑھ کی نیچریت کے اثرات کا نتیجہ ہو سکتا ہے جس کی طرف محدث رحیم آبادیؒ نے اشارہ کیا ہے مگر اس کا ایک اور سبب بھی ہے اور وہ یہ کہ حدیث و سنت کی تحقیق شبلی کا اصلی میدان نہ تھا؛ ان کی توجہات اور قلمی فتوحات کی خاص جولان گاہ تاریخ و سیر کے موضوعات تھے۔ یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ تاریخی روایات میں اصل مدار اسناد اور راویوں کے بجاے واقعات کی شہرت پر ہے؛ چناں چہ اکثر تاریخی روایات منقطع ہوتی ہیں اور ان کے راوی مجہول یا مجروح ہوتے ہیں۔ تاریخی وقائع کے بیان میں اس کمی کو ظن و تخمین اور عقلی توجیہات سے پورا کیا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نے درحقیقت اپنے اس موَرخانہ انتقادی شعور کو حدیثی انتقاد میں برتنے کی سعی کی ہے۔ اس کے لیے انھیں امام اعظم سے کچھ اشارات ملے کہ انھیں بھی احادیث و آثار کی قلت کے سبب سے قیاس اور استخراج سے کام لینا پڑا تھا۔ شبلی نے یہ سمجھا کہ ایسا شاید مخصوص درایتی اصولوں کی بنا پر تھا؛ یوں انھوں نے اپنے زورِ قلم اور پروازِ تخیل سے اس خاکے میں رنگ بھرنے کی کوشش کی اور نظریہ سازی کر کے اس کو علم حدیث و سیرت پر منطبق کرنے کا راستا اپنایا۔ واقعاتِ سیرت میں اگرچہ اس کی کچھ گنجایش نکل سکتی تھی مگر علم حدیث کو اس درایتی کسوٹی پر جانچنا بڑا خطرناک کام تھا جس سے یہ راستا کھل جاتا کہ ہر ناقد اپنی طبع کے تقاضوں اور عقلی نکتہ طرازیوں کی بنا پر روایات و آثار کو نقد و جرح کی سان چڑھا دیتا جیسا کہ بعد ازاں ہوا بھی اور بعض اہل فکر نے اسی درایت کی بنا پر صحیح احادیث کا انکار کر دیا۔ اب تو دبستانِ شبلی کے عنوان سے انکار و استخفافِ حدیث کی منظم مہم جاری ہے!
’’حسن البیان‘‘ برصغیر پاک و ہند میں تحریک عمل بالحدیث کی اہم علمی اور تاریخی دستاویز ہے جس کے مطالعے سے ان تمام مباحث سے آگہی حاصل ہوتی ہے جو اہل الحدیث اور اہل تقلید میں اہم اختلافی مسائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب آج سے لگ بھگ ایک سو بتیس برس پہلے (1311ھ/ 1893) شایع ہوئی؛ بعد ازاں اس کے مزید دو اڈیشن بھی اشاعت پذیر ہوئے لیکن وہ اس کے شایان شان نہ تھے۔ اب محسن ملت جناب ڈاکٹر بہاءالدین کی توجہ اور کاوش سے اس کا نقش جدید طبع ہوا ہے جو معنوی اور ظاہری محاسن سے مالا مال ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے کتاب کے موضوع کی مناسبت سے اس میں بہت سے قیمتی اضافے بھی کر دیے ہیں جن میں مناظرۂ مرشد آباد بنگال کی روداد اور پریوی کاؤنسل لندن کا فیصلہ خاصے کی چیز ہیں۔
مناظرے کا موضوع تقلید شخصی تھا جس میں حنفی مناظرین کا دعویٰ تھا کہ تقلید شخصی شرعاً واجب و لازم ہے؛ عاملین بالحدیث کے موقف کی نمایندگی محدث عبدالعزیز رحیم آبادیؒ نے کی اور ثابت کیا کہ حنفیہ کا دعویٰ دلائل سے خالی ہے اور کتاب و سنت کی کوئی نص تقلید شخصی کے وجوب پر موجود نہیں ہے۔ مناظرے کی تفصیلات بڑی دل چسپ اور علمی نکات کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔
پریوی کاؤنسل لندن کا فیصلہ بھی تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ احناف زور زبردستی سے اہل حدیث امام اور نمازیوں کو مسجد سے بے دخل کرنا چاہتے اور انھیں وہاں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ یہ قضیہ عدالت میں پہنچا جس کی پیروی کے لیے محدث رحیم آبادی کے والد گرامی شیخ احمد اللّٰہ رحیم آبادی مرحوم نے بھرپور کاوشیں کیں اور اُس زمانے میں پندرہ ہزار روپے خرچ کیے جو بڑی خطیر رقم ہے۔ فیصلہ عاملین بالحدیث کے حق میں ہوا اور مسجد کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اپنی موجودہ صورت میں یہ کتاب نہ صرف علمی مباحث کا نادر خزینہ ہے بل کہ ان تاریخی شہادتوں کا معتبر وثیقہ بھی ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عاملین بالحدیث کو اپنے جماعتی وجود اور فکری شناخت کی بقا کے لیے کن مشکل گھاٹیوں سے گزرنا پڑا ہے۔
محترم و مکرم ڈاکٹر بہاءالدین کی علمی اور دینی خدمات کا دائرہ بے حد وسیع ہے اور گذشتہ نصف صدی پر محیط ہے۔ انھوں نے بلا مبالغہ ہزاروں صفحات شایع کیے ہیں جن میں’’ تحریک ختم نبوت‘‘ کی 75 جلدیں (71 مطبوع) اور ’’تاریخ اہل حدیث‘‘ کی سولہ مجلدات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ وہ دیارِ فرنگ میں بیٹھ کر بے سر و سامانی کے عالم اور پیرانہ سالی کی حالت میں جو کارہاے نمایاں سرانجام دے رہے ہیں، وہ ناقابل یقین ہیں۔ مختلف ممالک کے اہل علم سے رابطے کر کے لوازمے کی جمع آوری، اس کی ترتیب و تدوین، اس کی مشینی کتابت اور اس کی حروف چینی کے جملہ مراحل تن تنہا طے کرتے ہوئے وہ اس کو طباعت کے لیے بھیجتے ہیں اور کتاب کی اشاعت کے بعد وہ اسے مختلف اہل علم و فکر تک پہنچانے کے لیے بھی خود ہدایات دیتے اور اس سارے عمل کی نگرانی اور سرپرستی کرتے ہیں۔ اب سوچیے بھلا یہ سارے کام ایک بوڑھا آدمی کر سکتا ہے جو مختلف عوارض اور امراض میں بھی گھرا ہو؟ عقل اس کا جواب نفی میں دے گی لیکن ایمان و یقین کی قوتیں ایسی مشکلات کو شکست دے کر ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہیں۔ یہ ان کے غیر معمولی عزم اور توکل علی اللّٰہ ہی کے ثمرات ہیں کہ پروردگار ان سے یہ عظیم الشان خدمت لے رہا ہے کہ وہ جماعت اہل حدیث کی علمی اور نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جماعتوں اور اداروں کے کرنے کے کام اکیلے محترم ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں۔ کاش ہم ان کے لیے ایک علمی اور تکنیکی ٹیم تشکیل دے پاتے جو ان کی نگرانی میں کام کرتی اور ڈاکٹر صاحب صرف علمی و فکری رہ نمائی کا فریضہ سر انجام دیتے لیکن: اے بسا آرزو کہ خاک شدہ!
دعا ہے کہ پروردگار محترم ڈاکٹر بہاء الدین کو ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے اور ان کی زندگی میں برکت دے کہ وہ ہمارے تاریخی دفاتر کو گم نامی کے پردوں سے نکال کر منصۂ شہود پر لاتے رہیں؛ آمین۔
[1] مجموع الفتاوى: 4/ 95
[2] تدوین فقہ و اصول فقہ: 83-84
[3] بہ حوالہ : مجالسِ محدث العصر، مرتبہ: مولانا فیصل احمد ندوی
یہ مبحث حسن البیان میں بھی آیا ہے اور محدث رحیم آبادیؒ نے بعض دیگر اہل علم کے حوالوں سے تدوین اصولِ فقہ کے باب میں امام شافعیؒ اولیت کا اثبات کیا ہے۔
[4] ارشاد القاصد به حواله تحفة الاحوذی
[5] قواعد التحديث للقاسمی: 75
[6] مفتاح السعادۃ