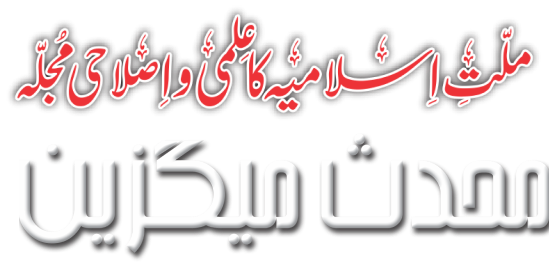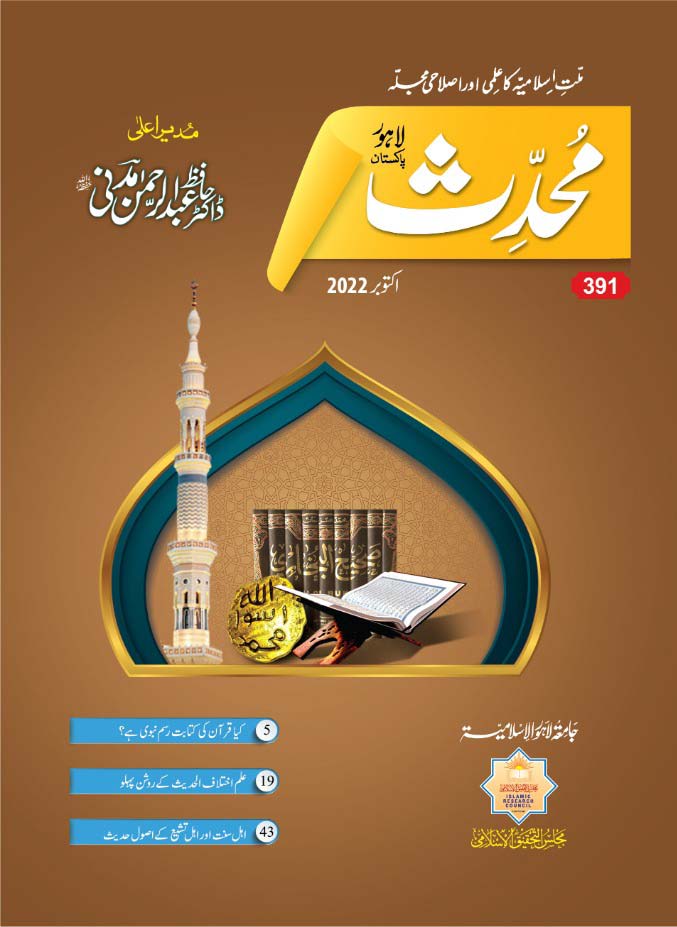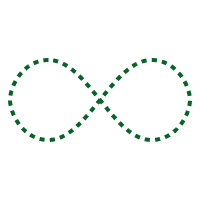شرح كتاب التوحيد (صحيح بخاری)
افادات: حافظ عبدالرحمن مدنی
ترتیب: حافظ عبدالرحمن عزیز
قسط (2)
شرح كتاب التوحيد (صحيح بخاری)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ ،أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ؟»، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:«أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟»، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ»
ہمیں محمد بن بشار نے ‘ ہمیں غندر نے بیان کیا، کہ ہمیں شعبہ ابو حصین اور اشعث بن سلیم سے بیان کیا ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا‘ وہ معاذ بن جبل ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ‘ اے معاذ ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے ؟ انہوں نے عرض کیا : اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اوراس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ۔(پھر ) آپ ﷺ نے فرمایا : کیا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (اگر وہ اللہ کا حق پورا کریں تو) وہ انہیں عذاب نہ دے ۔
لطائف الاسناد
مذکورہ سند میں تین راوی شعبہ ، ابومعین اور اشعث بن سلیم تبع تابعی ہیں ، اور پہلے چاروں ر اوی صحاح ستہ کی تمام کتب کے رواۃ ہیں ، گویا آئمہ حدیث کو ان رواۃ کے کمال عدالت و ثقاہت پر مکمل اعتماد ہے ۔
شرح الحدیث
اس حدیث سے امام بخاری دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں :
اولاً : توحید محض معرفت الٰہی یا اقرار کا نام نہیں ہے ، بلکہ اصل توحید یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندے پر اللہ کے کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں ، بندے کو چاہیے کہ انہیں پورا کرے ۔
ثانیاً : توحید الوہیت کا اثبات ، کہ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مان کر اس کے مطابق عمل کا ارادہ بھی کرے ۔ انبیاء اور کفار کے درمیان ہمیشہ سے یہی اختلاف رہا ہے کہ توحید کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے ، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور تمام قدرتوں کا مالک ہے ، یہ تو کفار قریش ( مشرکین) کو بھی تسلیم تھا ۔ لہٰذا محض توحید ربوبیت کا اقرار نجات کے لیے ناکافی ہے۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے یا توحید کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں ، جنہیں پورا کرنا بندوں کا فرض ہے ۔ ان میں دو حقوق بنیادی ہیں ، ایک ،بندہ اپنے خالق و مالک کی تمام قدرتوں (اسماء وصفات ) کا اقرار کرے ، دوسرا عقیدتًا اور عملاً بھی اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک (حصہ دار) نہ سمجھے ۔ اسی کو توحید عبادت اور توحید الوہیت کہتے ہیں ۔
اصطلاحاً یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت امام ابن تیمیہ کی تعبیر ہے۔ توحید ربوبیت توحید اسماء و صفات پر بھی مشتمل ہے ۔ امام ابن قیم نے توحید ربوبیت کو توحید ’ علمی خبری‘ کا نام اس لئے دیا ہے کہ عوام کو اجمالاً اور علماء کو تفصیلاً اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اسی بنیاد پر اس کا ارتقائی مرحلہ توحید ارادی طلبی ہوگا جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں ۔
مذکورہ بالا دو اقسام درا صل توحید کے دو مرحلے ہیں : ایک یہ کہ اللہ کی پہچان ہو کہ وہ اپنی ذات اور افعال کے اعتبار سے تنہا ہے ۔ دوسرا ، جب ہمارے علم میں یہ بات آگئی کہ اللہ اپنی ذات ، صفات اور افعال میں یکتا ہے تو ہم اس کے مطابق اپنی طلب و ارادہ سے عبادت بجا لائیں ۔
علم نحو میں اس کی مثال جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہے ۔ خبریہ جس میں دوسرے کو کسی واقعہ کی اطلاع دیتے ہیں ، جس سےاس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے ،جب کہ انشائیہ خبر کی بجائے دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے ، جیسے کھانا کھاؤ ، مت جا ؤ وغیرہ ۔
مثلاً بعت و اشتریت کے ذریعے اگر آپ کسی کو خبر دیں کہ فلاں چیز میں نے خرید لی ہے اور فلاں چیز میں نے بیچ دی ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے اور اسی جملے کو معاہدۃ خرید و فروخت کے وقت بولیں تو یہ ’انشاء ‘ ہے ۔ اسی طرح توحید کے بھی دو پہلو ہیں : علم اور عقید ہ۔ توحید علمی خبری کے اعتبار سے عام طور پر مسلمان اور کفار حتیٰ کہ شیطان بھی یکساں ہوتے ہیں ، کیونکہ شیطان کو بھی علم ہے کہ اللہ تنہا ہے ، بلکہ اس کو ہم سے زیادہ معرفت ہے۔ اس معرفت میں کفار ِ قریش مسلمانوں کے برابر تھے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے اقرار کا تذکرہ کیا گیا ہے: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ [العنكبوت: 61]
اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے اور یہ شمس و قمر کو کس نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے؟ کفار جواب یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کو خالق و مالک مانتے ہیں ، تو وہ مشرک کیونکر ہیں؟ ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کے خبری پہلو کو تسلیم کر رہے ہیں جبکہ انشائی تقاضے کو تسلیم نہیں کرتے ۔ چونکہ خبر کا مقصود اطلاع ہوتا ہے جبکہ انشاء کسی نئی چیز کو وجود میں لانا ہوتا ہے۔ گویا توحید معرفت یا توحید علمی خبری در اصل توحید طلبی ارادی (توحید انشائی) کی تمہید ہے اور توحید انشائی اصل مطلوب و مقصود ہے ، لہٰذا تمہید پر ایمان کے باوجود مقصود پر عدم ایمان تمہید کا بھی انکار ہی سمجھا جاتا ہے ۔
ابن قیم کی وضاحت کے مطابق انسان کا اللہ سے تعلق توحید طلبی کی صورت ہونا چاہیے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت کی بنا پر ہی وہ اس کی عبادت بجا لاتا ہے ، مثلاً ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو اللہ کی محبت و اطاعت کے طور پر نہیں بلکہ کسی طبی فوائد کے لیےپڑھتا تو یہ نماز بےکار ہے، کیونکہ نماز کے پیچھے طلب خدا وندی موجود نہیں ہے ۔ اسی طرح محبت اور ایمان کی کمی بیشی کی بنیاد پر عمل کا ثواب ملتا ہے چنانچہ ایک فرمان نبوی ؐ یوں ہے کہ تمام نماز پڑھنے والے برابر نہیں ہوتے ۔ نماز کے دس حصوں میں ایک سے لیکر کامل نماز تک کا اجر مختلف لوگوں کو فرقوں سے ملتا ہے ، اس کی وجہ یہی ہے کہ طلب و محبت جس درجہ کی ہے اسی کے مطابق ثواب ہو گا ۔ قرآن مجید نے اسی کو خشوع و خضوع سے تعبیر کیا ہے کہ جس میں طلب و محبت اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہوتی ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:
(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)[المؤمنون :1،2]
’’ ایماندار لوگ کامیاب ہوگئے ۔ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں ۔ ‘‘
قدیم مسلمان فلاسفہ کا یہ بڑا نقص ہے کہ انہوں نے توحید سے مراد صرف علم لیا گیا ، یا علم کی اعلیٰ ترین شکل کو ہی کو توحید کی انتہاء قرار دے دیا گیا ہے ، قرون اولی میں انہیں جہمیہ کہا جاتا تھا ۔ جبکہ علمائے سلف کا موقف یہ ہے کہ علم و عمل دونوں ایمان کی بنا پر ہوتے ہیں ، اصل توحید محبت الہی ہے جو کیفیت قلبی ہوتی ہے اسلام اور ایمان کا تقابلی ذکر ہو تو یہی کیفیت ایمانی علم و عمل میں کمی بیشی کی بنیاد ہوتی ہے ۔ سلف کا قول الایمان قول و فعل يزيد و ينقصمشہور ہے۔ ارادہ کے بعد نیت پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے ۔ چنانچہ نبیﷺ نے فرمایا:
«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»[1]
’’اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ، ہر بندے کو وہی ملتاہے جس کی اس نےنیت کی ہو ، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے وہ مل جائے گی ، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو وہ اس سے نکاح کرلے گا ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی نیت سے ہجرت کی ہو۔‘‘
مزید آپ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد فرمایا:
«لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ»[2]
’’ فتح مکہ کے بعد ( دیگر علاقوں سے )ہجرت ختم ہوگئی ، لیکن جہاد اور ( غلبئہ دین کی ) نیت باقی ہے‘‘
عمل کا آغاز ارادہ کے بعد نیت سے ہوتا ہے ، اور یہی اس کی قبولیت کا معیار ہے ۔ جنگ تبوک میں جب صدقہ کا مطالبہ کیا گیا تو حضرت عمر ؓ مال لانے کے اعتبارسے حضرت ابوبکر ؓسے برتر تھے ، لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ نیت کے اعتبار سے افضل قرار پائے ۔
انبیاء کرام صرف علم اور معرفت کے لیے نہیں آتے ، بلکہ وہ انسانوں میں طلب و ارادہ پیدا کرنے کی غرض سے تشریف لاتے ہیں ۔
توحید کے معنی و مفہوم میں ایک بڑا بگاڑ اہل تصوف نے بھی پیدا کیا ہے ، اہل تصوف کا موقف ہے کہ توحید کا اصل مقصود معرفت ہے ، نہ کہ عبادت ۔اسے ثابت کرنے کے لیے ایک موضوع روایت کا سہارا لیا جاتا ہے :
(كنت كنزا مخفيا. فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني)[3]
’’ میں ا یک پوشیدہ خزانہ تھا ، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو ، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا کیا جس کی بدولت میری پہچان ہوئی ۔‘‘
امام العجلونی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صوفیا کے کلام میں پائی جاتی ہے جسے نبی ﷺ کی طرف منسوب کرنا جھوٹ ہے ، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ﷺ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح یا ضعیف سند ہے۔
المختصر ! توحید کے معاملے میں جب علم کے پہلو سے بات ہو گی تب وہ توحید ربوبیت کہلائے گی، خواہ وہ اسماء وصفات کی بحث ہو ۔ لیکن جب ان کے مطابق طلب و ارادہ کی بات ہو گی تو یہ توحید الوہیت بن جائے گی ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی کیفیت قلبی کے اعتبار سے توحید الوہیت کی بحث بن جائے گی ۔
ایمان کی بنیاد طلب ہوتی ہے ،اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان’ کیفیت ‘ کا نام ہے ۔مجھے یاد ہےکہ شیخ التفسیر حافظ محمد حسین امرتسری اور تایا مرحوم حافظ عبد اللہ (محدث) روپڑی کے درمیان اکثر مذاکرہ و بحث ہوئی کہ فن منطق کے اعتبار سے ایمان مقولہ ’کم‘ میں سے ہے یا مقولہ ’کیف ‘میں سے ؟ دونوں ہی اس پر متفق ہوئے کہ ایمان ’مقولہ کیف ‘ سے ہے ۔ مقولہ کیف کا معنیٰ ہے کہ ایمان اصل میں انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے ۔ جیسے جیسے وہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ایمان میں اضافہ اور پختگی آتی جاتی ہے ۔ اگر انسان میں ایمانی کیفیت پیدا نہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت ، ذکر و اذکار اور عبادات کاثواب اگر مل بھی جائے تب بھی اس کاتربیتی ، نفسیاتی اور روحانی فائدہ بہت کم حاصل ہوتا ہے ۔حدیث جبریل میں اسلام اور ایمان دونوں کے امتزاج والی حالت کو ’احسا ن‘ کا نام دیا گیا ہے ، رسول اللہ ﷺ سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا :
احسان کیا ہے ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ»[4]
’’تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے ۔‘‘
اسی لیے دعا کو عبادت کا اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا ہے کہ اس سے انسان میں دوسری عبادات کی نسبت طلب کا زور ہوتا ہے۔ چونکہ اسی طلب کی بڑھوتری اللہ تعالیٰ کو زیادہ مطلوب ہے ، دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
{قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ } [الفرقان: 77]
’’ (اے نبی ! آپ لوگوں سے ) کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے نہ پکارو تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پروا نہ ہوتی ۔‘‘
مزید حضرت زکریا کے متعلق فرمایا:
{ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَريَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} [مریم :2-4]
’’ یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی ۔ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا ۔ اور کہا : ’’ میرے پروردگار ! میری ہڈیاں بوسیدہ ہوچکیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہوگئے ، تاہم اے میرے پروردگار ! میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا ۔ ‘‘
اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر دو بنیادی حقوق ہیں (1) اللہ کی عبادت کرنا (2) اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ، عبادت سے مراد ہر وہ کام جو کسی کو خوش کرنے کے لیے انجام دیا جائے ، چونکہ اللہ سب کا خالق و مالک ہے لہذا اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی عبادت کا حق یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پوری طرح بجا آوری کی جائے اور منع کردہ کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی لیے عبادت کرنا اور شرک نہ کرنا دو مختلف چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں ۔ یعنی شرک نہ کرنا عبادت کرنے کا ہی دوسرا رخ ہے ۔ شرک کی موجودگی میں عبادت بے کار اور لا حاصل ہوتی ہے اسی لیے قرآن و حدیث میں عبادت کرنے اور شرک سے اجتناب کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے ۔
اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک سے کلی اجتناب کرے ، تو اللہ پر بندےکا یہ حق لازم ہوجاتا ہے کہ اسے عذاب نہ دے ، یعنی بخش دے ۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حق بندےنے اللہ پر لاگو نہیں کیا ، بلکہ خود اللہ نے اپنےاوپر لازم کیا ہے ،جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
{وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } [الروم: 47]
" اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔"(یہ تفسیری نکتہ ہے ورنہ اس آیت کے کئی مفاہیم ہیں )
مزید فرمایا :
{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 54]
’’ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کرلیا ہے ۔‘‘
قرآن مجید اور احادیث میں کئی مقامات پر جنت و جہنم ،عذاب و مغفرت کو شرک سے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے ۔ یعنی شرک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو گا اور شرک سے اجتناب کرنے والا مغفرت اور جنت کا حق دار ہو گا۔
عبادت کی ضد شرک ہے ۔ جب انسان معرفت کے باوجود طلب و ارادہ کا مستحق اللہ رب العالمین کے سوا کسی دوسرے کو بھی بنا لیتا ہے تو وہ عبادت کو بھی منہدم کردیتا ہے ، اس لیے یہ سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔
قرآن کریم میں ہے:
{ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]
اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔
مزید فرمایا:
{وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [المائدة: 72]
’’حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا : ’’ اے بنی اسرائیل ! اللہ کی عبادت کرو ، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مدد گار نہ ہوگا ۔‘‘
اور حدیث قدسی میں ہے :
يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً .[5]
(اللہ تعالیٰ نے فرمایا:)اے آدم کے بیٹے ! اگرتو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھرمجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔(شرک کے ما سوا دیگر گناہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں وہ پکڑے یا چھوڑ دے )
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» . [6]
حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا، اور عرض کرنے لگا : اے رسول اللہ ﷺ ! وہ کون سی دوچیزیں (جنت اور جہنم کو ) واجب کردینے والی ہیں ؟:آپ ﷺنے فرمایا: جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جوشخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
عَنِ أَبِيْ ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ .[7]
حضرت ابوذر ؓبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل ؑ آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو گا تو وہ جنت میں جائے گا۔
ملاحظہ : مشیت الہی کی بحث آگے آ رہی ہے ، لہذا بے عملی کی جرأت بڑی خطرناک شے ہے ۔ اس کی وضاحت ہم کسی دوسرے موقع پر کریں گے۔ ان شاءاللہ
اہم فوائد
- توحید محض معرفت الٰہیہ کا نام نہیں ہے ، بلکہ معرفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے بندےکے تعلق قائم کرنے کا نام ہے ۔
- معرفت تو محض بنیاد ہے ورنہ اصل مقصود یہ ہے کہ بندےمیں طلب و ارادہ پیدا ہو ۔
- اللہ تعالیٰ کابندے پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
- اگر بندہ شرک سے پرہیز کرے ، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت عطا کر سکتے ہیں ، لیکن شرک اکبر کسی صورت معاف نہیں ہو گا ، اس کی سزا صرف جہنم ہے ۔
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ »زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))
ہمیں اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے بیان کیا ‘ ان سے عبد الرحمن بن عبد اللہ ابن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ نے بیان کیا ‘ ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری ؓ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو(نماز تہجد میں ) بار بار قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا گویا وہ اسے ہلکا سمجھ رہا تھا ۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا : اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ! یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے ۔
اسماعیل بن جعفر نے امام مالک سے یہ اضافہ ذکر کیا ہے کہ انہیں عبد الرحمن نے ‘ اپنے والد سے بیان کیا کہ ابو سعید خدری ؓ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی قتادہ بن نعمان نے نبی کریم ﷺ سے یہ خبر دی ہے ۔
لطائف اسناد
اس حدیث کو امام بخاری نے دو اسناد سے ذکر کیاہے ، اوردوسری سند میں صرف امام بخاری کے استاذ کا فرق ہے ، حسن اتفاق سے دونوں اسنادمیں امام بخاری کے دونوں اساتذہ کے نام اسماعیل ہیں ، پہلی سند میں إِسْمَاعِيل بن أبي أويس ہے ، جب کہ دوسری سند کے پہلے راوی کا نام اسماعیل بن جعفر ہے اور وہ دونوں ہی امام مالک سےروایت کرتے ہیں ، باقی راوی یکساں ہیں ۔
پہلی سند میں حضرت ابو سعید خدری ؓ ’رجل ‘ کے واسطہ سے نقل کررہے ہیں ، جبکہ دوسری سند میں رجل کی تعیین کر رہے ہیں کہ وہ ان کا اخیافی (ماں جایا) بھائی قتادہ بن نعمانؓ تھا ۔
اگر صحابی رجل (مبہم ) بیان کرے یا نام ذکر کرے تو دونوں صورتوں روایت صحیح ہوتی ہے بشرط یہ کہ صحابی ہو کیونکہ صحابہ کلہم عدول ہیں ۔ البتہ نام ذکر کرنے سے صراحت ہو جاتی ہے ۔
مذکورہ حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ صاحب واقعہ کون تھا ، لیکن دوسری روایت[صحیح بخاری : 5014] میں وضاحت ہے کہ صاحب واقعہ حضرت ابو سعید کے ماں شریک بھائی قتادہ بن نعمان ہیں اور راوی قصہ بھی ہیں ۔نعمان ان سے بڑے اور بدری ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری
اس حدیث کےراوی ابو سعید خدریؓ ہیں ، جن کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان خدری ہے ، مدینہ کے رہنے والے ہیں ، ہجرت کے وقت ان کی عمر دس برس تھی ، آپ کے والد مالک بن سنان صحابی ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ا ٓپ جنگ احد میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوئے لیکن کم عمری کے سبب لوٹا دیئے گئے ، پہلی مرتبہ آپ کو جنگ خندق میں شرکت کی اجازت ملی ، اس کے بعد ہر جنگ میں نبي ﷺ کے ساتھ شریک کار رہے ، سن 74 ہجری میں ا ٓپ کی وفات ہوئی ، اور بقیع میں دفن ہوئے ، کثیر الروایۃ صحابہ میں سے ہیں ۔
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ {بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:«سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ »[8]
ہمیں محمد نے بیان کیا ، کہ ہمیں احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہمیں ابن وہب نے عمرو سے بیان کیا ‘کہ انہیں ابوہلال نے بیان کیا کہ ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن نے ‘ اپنی والدہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے بیان کیا کہ ‘ وہ ام المؤمنین عائشہ ؓ کی پرورش میں تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ ؓ سے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صاحب کو ایک مہم پر روانہ کیا ۔ وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز میں (قراءت کا اختتام ) قل ھو اللہ احد پر کرتے تھے ۔ جب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر آنحضرت ﷺ سے کیا ۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند رکھتا ہوں ۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ انہیں بتا دوں کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے ۔
لطائف الاسناد
مذکورہ حدیث کی سند میں پہلا راوی محمد چونکہ بغیر کسی نسبت کے ذکر کیا گیا ہے ، اس لیے شارحین میں اختلاف ہے کہ یہ محمد کون ہے؟ امام بیہقی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ محمد بن یحیی الذھلی ہے ، اس لیے الاسماعیلی نے المستخرج میں حرملۃ عن ابن وہب کی روایت میں محمد بن یحیی الذھلی کانام لکھا ہے ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں محمد سے مراد امام بخاری ہیں ، یعنی صحیح البخاری کو نقل کرنے والے امام بخاری کے شاگرد امام فربری نے اپنے اعتبار سے امام بخاری کانام لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ روایت امام بخاری سے لی ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری صحیح بخاری میں ہر جگہ پر احمد بن صالح سے امام بخاری بلا واسطہ نقل کرتے ہیں ، کہیں بھی بالواسطہ نقل نہیں کی ۔ و اللہ اعلم
راویہ حدیث : سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
ام المؤمنین سیدہ عائشہ ؓ ،حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں ، رسول اللہ ﷺ نے ان سے غزوہ بدر کے بعد سن دو ہجری میں شادی کی ۔ ان کے بقول شادی کے وقت ان کی عمر 9 برس تھی ، اس طرح آ پ کی پیدائش سن 8 نبوی بنتی ہے ۔ آپ بہت بڑی فقیہہ اور عالمہ تھیں ، صحابہ کرام مشکل مسائل ان سےحل کراتے تھے ۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں :
« مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِّ مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ»[9] "
میں نے ام المؤمین سیدہ عائشہ سے بڑھ کر حلال و حرام ، شعر، طب اور دوسرے علوم کو جاننے والا نہیں دیکھا ۔
شرح الحدیث
مذکورہ بالا دونوں احادیث لانےکا مقصداللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی وحدانیت کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ اور یہ بتانا ہے کہ توحید بنیادی اور اعلیٰ ترین علم ہے ۔
اور دوسری احادیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت کرنے اور اس کے اسماءو صفات ذکر کرنے کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جو شخص اللہ کی صفات سے محبت کرتاہے ، اور ان کی تلاوت کرتاہے ، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنےلگتے ہیں ۔
اللہ کی صفات کو ماننا اور ان سے محبت کرنا توحید الوھیت ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ۔
سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف پیش کیاگیاہے ۔ اس میں اللہ کی وحدانیت ، اس کی بے نیازی ، رشتہ داری اور ہمسری کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اعلی حیثیت پیش کی گئ ہے ۔
حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے کہا : اےمحمد ! اپنے رب کا نسب بیان کریں ، اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی ۔[10]
سورۃ الاخلاص کی فضیلت :
سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جن کی روشنی میں اس کی یکتائی پر زور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہیں ۔ پر مشتمل ہے ۔شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کی تفسیر کرتےہوئے فرماتے ہیں :
" بعض علماء نے کہا ہے کہ شرک کبھی تعدد کی صورت ہوتا ہے ، جس کی لفظ احد کہہ کر نفی کردی گئی ہے ، اور کبھی شرک مرتبہ و منصب کے اعتبار سے ہوتا ہے ، اس کی نفی لفظ صمد سے کی گئی ہے ۔ اسی طرح رشتہ داری کی نسبت سے بھی ہوتا ہے ، لم یلد و لم یولد کہہ کر اس کی نفی کی گئی ہے ۔اور کبھی شرک کام اور تاثیر میں دخل اندازی سے ہوتا ہے اس کی نفی لفظ ولم یکن له کفوا أحد سے کی گئی ہے ۔ توحید کے اسی جامع مضمون کے باعث اس سورت کو " سورۃ الاخلاص " کہا جاتا ہے ۔[11]"
مزید اس سورت میں شرک و الحاد کے جتنےنظریات دنیا میں موجود ہیں ، سب کا ردّ موجود ہے ۔
ثلث القرآن کی وجوہات
مذکورہ بالا حدیث میں سورۃ الاخلاص کو ثلث القرآن قرار دیا گیا ہے ،اس کی علماء کرام نے کئی توجیہات کی ہیں ۔
پہلی توجیہ :
قرآن مجید میں بنیادی طور پر تین مضامین بیان ہوئے ہیں ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ، عبادات اور معاملات ۔ سورۃ الاخلاص ان میں سے توحید کا جامع ترین تعارف ہے ، اس لیے اسے ثلث القرآن کہا گیا ہے ۔
دوسری توجیہ :
قرآن مجید کے تین حصے ہیں : عقیدہ ، قصص کی عبرت و نصیحت ، اور شرعی احکام ۔ سورۃ الاخلاص ان میں سے عقیدہ والے حصے( توحید )کی تمام جہتوں پر مشتمل ہے ، اس لیے اسے ثلث القرآن کہا گیا ہے ۔
تیسری توجیہ :
قرآن مجید میں تین عقائد بیان ہوئے ہیں توحید ، رسالت ،اور آخرت اور سورۃ الاخلاص ان میں سے اہم ترین عقیدہ توحید پر مشتمل ہے ۔
چوتھی توجیہ :
قرآن مجید کی بعض آیات کا دوسری آیات پر یک گونہ اضافہ ہوتا ، اسی اصول کے مطابق سورۃ الاخلاص ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے ۔ یہ تمام توجیہات اس سورۃ پر صادق آتی ہیں ۔
امام بخاری مذکورہ بالااحادیث کو اس باب میں اس لیے لائے ہیں کہ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کا تعارف اور توحید کی دیگر اعمالِ خیر پر بالا دستی پر مبنی ہے ، یعنی یہ توحید خالص کی جامع ترین سورت ہے ۔ لہٰذا اسے غور و خوض سے پڑھنا اور اس سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے ۔
فوائد :
- سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کے تعارف اور اس کی اعلی صفات پر مشتمل ہے ۔
- اللہ تعالیٰ کی صفات سے محبت اللہ کی ذات سےمحبت کی بنا پر ہی ہوتی ہے ، گویا بندہ کا اللہ کی ذات و صفات سےمحبت کرنا محبت ربانی کے حصول کا سبب ہے ۔
- اللہ تعالیٰ کی کلام سے خالص محبت کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دیتے ہیں ۔
- اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے مرجع محبت کا اثبات ہے ۔
- سورۃ الاخلاص ’ثلث قرآن ‘کے برابر اجر کی حامل ہے ۔
- نماز میں بار بار ایک ہی سورت بھی پڑھی جاسکتی ہے ۔
- قرآن کا کوئی حصہ بیک وقت تکرار سے پڑھا جا سکتا ہے ۔
- ایک ہی رکعت میں مختلف مقامات سے قرآن پڑھا جاسکتا ہے ۔
- صحابہ کرام نے اپنے امام کےایک عمل کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا : اس سے پوچھ کر آؤ وہ ایسا کیوں کرتا ہے ۔ لہذا جب کسی مفتی سے کسی شخص کے عمل کی بابت نسبت فتویٰ پوچھا جائے تو وہ جلد بازی نہ کرے ، بلکہ عمل کرنے والے کا نقطہ نظر ضرور جانے ،پھر فتویٰ دے۔
مولانا عبدالرؤف بن عبدالحنان سندھو کا سانح ارتحال مولانا عبدالرؤف بن عبدالحنان سندھو 18 جولائی 1956 کو گاؤں سندھو کلاں میں پیدا ہوئے ، ان کے دادا مرحوم مولانا محمد اشرف سندھو اپنے وقت کے عظیم عالم اور اعلیٰ پائے کے مصنف تھے ۔ بیٹے اور پوتے نے اس روایت کو ٹوٹنے نہیں دیا ۔ آپ نے پتوکی کے قریب گاؤں ’پاروکی ‘ میں قرآن مجید حفظ کیا ، پھر جامعہ الاسلامیہ اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں درس نظامی کیا ، دوران تعلیم ہی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوگیا ۔ وہاں سے فراغت کے بعد پہلے شارجہ پھر کویت میں دعوت و ارشاد اور تصنیف و تحقیق کے شعبوں سے وابستہ رہے ۔ آپ کی اکثر تصانیف عربی زبان میں اور تحقیقی انداز کی ہے جو عرب ممالک میں شائع ہو کر علماء سے داد تحسین وصول کرچکی ہیں ۔ شیخ کویت ہی میں تھے کہ بیماری نے آلیا ، ابتدائی علاج معالجہ کرایا مگر دل مطمئن نہ ہوا تو بچوں سمیت پاکستان تشریف لے آئے ، 8 اگست کو طبیعت زیادہ بگڑ گئی ، تو لاہور C.M.Hمیں لایا گیا ، تشخیص سے پتہ چلا کہ خطرناک قسم کا بلڈ کینسر ہے ۔ چار پانچ دن نیم بیہوشی میں رہنے کے بعد 14 اگست 2022ء بروز اتوار عشا کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ۔ انا لله وانا الیه راجعون ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی نے اپنے رفقا کے ساتھ جنازے میں شرکت فرمائی ۔ ادارہ محدث ان کے ورثاء اور جماعت کے غم میں برابر شریک ہے ۔۔(محدث) |
[1] صحيح البخاری :1
[2] صحيح البخاری :2783
[3] كشف الخفاء برقم 2016
[4] صحیح بخاری :50
[5] سنن الترمذي:3540
[6] صحيح مسلم:93
[7] صحيح البخاري :7487
[8] صحیح بخاری :7375
[9] المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 12):6733
[10] المستدرک :2/540
[11] تفسیر عزیزی از عبدالعزیز محد ث دھلوی