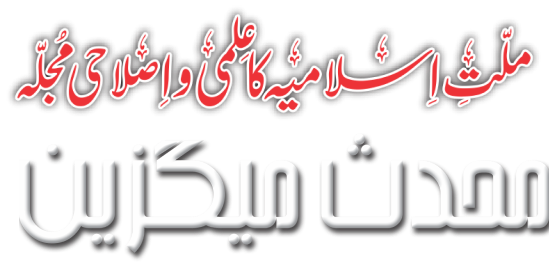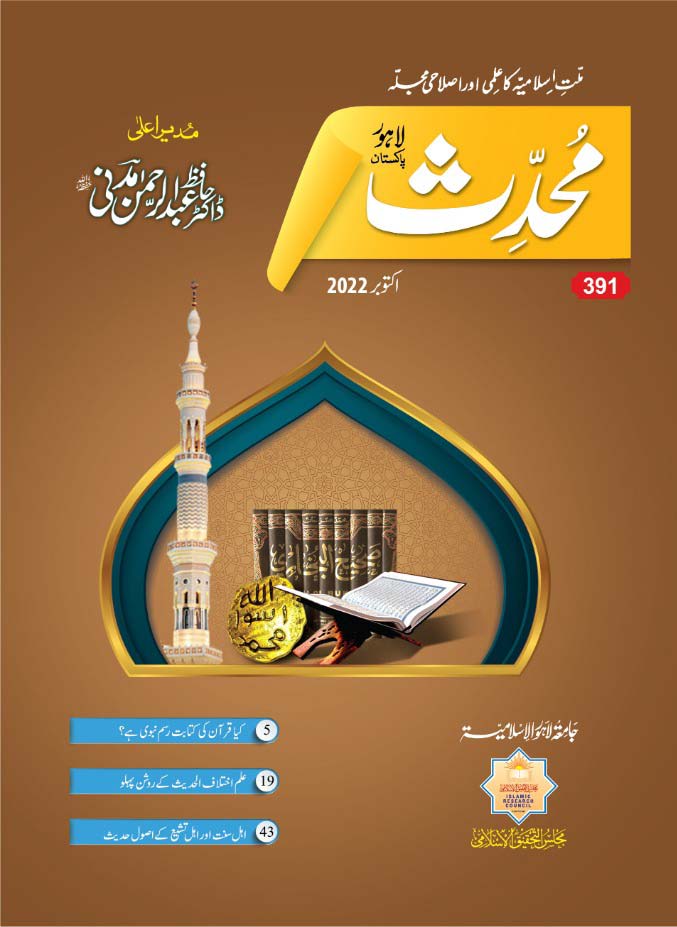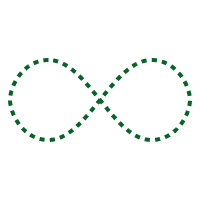عقیدہ و عمل میں سلفی؍ اہل حدیث کے امتیازات
ڈاکٹر آصف جاوید
عقیدہ و عمل میں سلفی؍ اہل حدیث کے امتیازات
برصغیر پاک و ہند میں ایک مذہبی فرقہ ’اہل حدیث‘ کہلاتا ہے اور عقیدہ وعمل کے میدان میں دورِ تقلید سے قبل کے ائمہ سلف سے منسوب ہو کر ’سلفی‘ لقب کا دعویدار بھی ہے۔ ’محدث‘ کی مجلس تحریر کے ایک رکن ڈاکٹر آصف جاوید کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ بھی اسی موضوع پرہے۔ملت اسلامیہ کا علمی اور اصلاحی مجلہ نفاذ شریعت کی راہ میں مذہبی فرقہ بندی کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے جیسا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کا حلقہ علم اور مولانا داؤد غزنوی وغیرہ کا زور اہل حدیث کے ملت اسلامیہ کے نمائندہ مکتب فکر ہونے کا تھا اور بقول مولاناعطاء اللہ حنیف مولانا محمد اسمعیل سلفی کو فکری طور پر اس موضوع پر مولانا داؤد غزنوی سے کئی دفعہ مباحثہ بھی کرتے سنا گیا ۔ برصغیر کے اہل حدیث تنظیمی طور پر عموماً عوام ہیں جبکہ ائمہ سلف کے اختلافات اہل علم کے تھے۔ ادارہ نے مقالہ مذکورہ کا یہ حصہ اس لیے شائع کیا ہے کہ علمائے اہل حدیث کی تازہ آراء بھی سامنے آ جائیں کیونکہ بلاد خلیج میں حنفی ،شافعی ،مالکی، حنبلی وغیرہ فقہی مکاتب فکر بھی عقیدہ میں ’سلفی‘ کہلاتے ہیں۔اہل حدیث کے تاریخی ارتقاء پر و قیع تجزیوں کی روشنی میں ہی ’محدث‘ اہل حدیث کے روشن مستقبل پر اصلاحی تجاویز دینا چاہتا ہے۔ لہذا اہل حدیث علم وقلم کو کتاب وسنت کی حدود میں آزادانہ شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ ( محدث) |
رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے ابتدائی قرون ثلاثہ کو بہترین قرار دیا ہے [1] ۔ اس زمانہ مبارک میں اہل کلام، اہل سنت ، اہل حدیث،اہل رائے نام کا کوئی گروہ موجود نہ تھا بلکہ تمام کے تمام لوگ اہل اسلام ہی تھے جو عقیدہ و عمل کے باب میں کتاب و سنت پرعمل کرتے تھے۔
ا ٓپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہو گی جب تک میری امت گزرے لوگوں کی روش اختیار نہ کرے گی ۔ [2] آپ کے فرمودات کے عین مطابق امت میں اختلاف و افتراق کی بنا پر مختلف فرقے وجود میں آئے، جن میں سے بعض کی بنیاد سیاسی نزاع اور بعض کی بنیاد مذہبی اختلاف تھا۔ سیاسی نزاع بعد میں اگرچہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا اور اصل مسئلہ کو گڈ مڈ کر دیا گیا ۔ اسی سیاسی نزاع کی بنیاد پر عثمانی و سبائی اور خوارج و روافض کا وجود عمل میں آیا جبکہ مذہبی اختلاف کی بنا پر قدریہ، جہمیہ ،معتزلہ اور مرجئہ کے فرق وجود میں آئے ۔ مذکورہ مذہبی فرقوں میں سے بعض فرقے کسی دوسرے کا رد عمل ہیں اور اپنے اصول کے لحاظ سے اس کی ضد میں واقع ہوئے ہیں چنانچہ خوارج کی ضد روافض ہے، قدریہ کی ضد جبریہ ہیں، معتزلہ کی ضد مجسمہ ہیں اور مرجئہ کی ضد وعیدیہ ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹیؒ رقم فرما ہیں:
’’ان سب کے پیدا ہوجانے کی جامع وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے خیالات و قیاسات کو داخل شریعت کیا اور اس طریق کو ملحوظ نہ رکھا جس پر آں حضرتؐ نے اپنی پاک جماعت؛ صحابہ کرامؓ کو چھوڑا تھا اور وہ صدر اول سے ان کے اوقات تک برابر متوارث چلا آرہا تھا۔‘‘ [3]
تاریخ اسلام میں جس فکر نے سادہ اسلامی فکر کو انتہائی متاثر کیا، وہ اعتزالی فکر ہے، جس کا آغاز ۱۰۰ ہجری کے گرد و پیش ہو گیا تھا جب حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے عرض کیا کہ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور مرجئہ کے نزدیک گناہ کسی مومن کو مطلقا کوئی ضرر نہیں دیتا ، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی آپ خاموش ہی تھے کہ آپ کے تلامذہ میں سے ایک شخص واصل بن عطا گویا ہوا کہ مرتکب کبیرہ کا حکم ان کے بین بین ہے نہ ہی وہ مومن ہے اور نہ ہی کافر ہے۔ واصل یہ کہتے ہوئے ایک ستون کے پاس چلا گیا جس پر آپؒ نے فرمایا:
اعتزل عنا الواصل [4]
’’واصل ہم سے الگ ہو گیا ہے۔‘‘
واصل نے بعد میں اپنے عقائد و نظریات کا پرچار شروع کر دیا اور معتزلہ کا بانی قرار پایا۔ فکر اعتزال کو اصل فروغ عباسی خلیفہ مامون کے عہد (۱۹۸تا ۲۱۸ھ) میں حاصل ہوا، جب اس نے یونانی علوم کا عربی میں ترجمہ کروایا جس سے فلسفہ یونان مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا ،بعض لوگ اس سے متأثر ہو کر عقائد اسلامی پر آزادانہ گفتگو کرنے لگے ۔معتزلہ کے پیشوا ابوہذیل علاف اور ابراہیم نظام کو مجلس مناظرہ کا سرخیل ہونے کاشرف حاصل تھا۔ یہ انہی کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا کہ مامون کے ذہن میں بھی خلق قرآن کا عقیدہ بیٹھ گیا اور اس نے جبر و تشدد کے بل پر اسے منوانا شروع کر دیا ۔امام احمد بن حنبلؒ نے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور عقیدہ خلق قرآن سے انکارکر دیا۔ فتنہ کے اس دور تک امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا انتقال ہو چکا تھا چنانچہ امام احمد ؒ کوامام اہل سنت کا لقب دیا گیا۔
ابتدائی اہل اسلام نام کے اعتبار سے اگرچہ اہل سنت نہ تھے مگر فکری اور معنوی طور پر ان کے پاس سنت رسول کا متعین پیمانہ موجود تھا اور وہ اسی پر کاربند تھے ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ رقم کرتے ہیں:
’’ اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں گو اہل سنت کا لفظ بحیثیت لقب نہ تھا مگر بحیثیت معنی کے سب صحابہ کرامؓ اہل سنت تھے۔ اہل سنت کے اضافی معنی صاف ہیں: سنت والا۔ یعنی وہ شخص یا فرقہ جس کو ہر مذہبی کلام میں سنت نبویہ ملحو ظ ہو… جو فرقہ صرف اس وحی الہی کو دستور العمل بنائے گا ، جس کو آنحضرتﷺ اور صحابہؓ نے بنایا وہ فرقہ اہل سنت ہے۔‘‘ [5]
آپؐ نے حضرات صحابہ کرامؓ کو اپنی سنت کی اتباع کا حکم دے رکھا تھا اور ساتھ ہی خلفائے راشدین کی سنت سے تمسک کا حکم بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا جاری کردہ عمل بھی قابل اتباع ہو گا اور اس سے انحراف کرنا جائز نہ ہو گا۔[6]لہذا جو گروہ سنت رسولؐ کے ساتھ ساتھ سنت خلفائے راشدین یا عمل صحابہ کرامؓ کی بات کرے گا، وہ اہل سنت قرار پائے گا جسے آپؐ نے حدیث میں ناجی فرقہ سے تعبیر کیا ہے اور ما انا عليه و اصحابی کو اس کا پیمانہ قراردیا ہے۔ ما انا عليه و اصحابی کا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں اضافت کیسی ہے؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل حدیث فکر کی رو سے اس میں صحابہ کرام کو عزت دینا مقصود دنہیں ہے بلکہ ان کی روش کو نجات کا ضامن قرار دینا مقصود ہے۔ حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ رقم فرماتے ہیں:
’’معطوف اور معطوف علیہ دونوں ناجی فرقہ کی علامت ہے کیونکہ دونوں ناجی فرقہ کی علامت کے سوال کے جواب میں واقع ہوئے ہیں …… رسول اللہﷺ کو معلوم تھا کہ فرقہ بندیوں کے وقت وحی الہی کو سمجھنے میں لوگ کھینچا تانی کریں گے اس لیے ساتھ صحابہ کو شامل کر دیا ۔ پس جو شخص تفسیر یا فتوی میں صحابہ کی جماعت سے الگ ہو جائے وہ وحی کا متبع نہیں ہے اور جو وحی کا متبع نہیں، وہ ناجی نہیں ہو سکتا۔‘‘ [7]
رسول اللہﷺ کی احادیث و سنن کی صحیح بنیادوں پر تفہیم کے لیے صحابہ کرامؓ کے فہم کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے وگرنہ گمراہی کا شکار ہونا یقینی ہو گا۔ یہی باعث ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک ’اہل السنۃ والجماعۃ‘ کی ترکیب میں ’السنۃ‘ سے مراد اتباع حدیث اور ’الجماعۃ‘ کی قید سے جماعت صحابہ کی روش مراد ہے۔
مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ رقم فرما ہیں:
’’اہل سنت اس جماعتِ حقہ کا نام ہے جو بلا کم و کاست مطابق اقوال و افعال رسولؐ اور مطابق اقوال و افعال صحابہ کرامؓ کے عمل کرتی ہے۔ اقوال و افعال رسول سے تو گریز نہیں لیکن ا قوال و افعال صحابہ کرامؓ اس لیے کہ انہی حضرات کے راہ حق پر چلنے کی دعا ہر نماز پنجگانہ میں کی جاتی ہے: {صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ} اور جس کی تفصیل {فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْھِمْ مِّنَ النَّبِیّٖنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصّٰلِحِیْنَ } میں موجود ہے۔‘‘ [8]
اہل سنت اور اہل بدعت
قرن اول کے نصف ثانی میں اپنے فضائل و مناقب اور مخالف کے عیوب و نقائص ثابت کرنے کی غرض سے مختلف فرقوں خصوصا خوارج و روافض نے وضع حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا تھا چنانچہ ان کے خود ساختہ عقائد و اعمال کی بنا پر علمائے اہل سنت نے انہیں اہل بدعت قرار دیا اور حدیث کی نقل و روایت میں اہل بدعت سے خبر دار رہنے کا اسنادی طریقہ کار اختیار کیا۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام صاحبؒ نے اپنی اسناد کے ساتھ محمد بن سیرینؒ تابعی سے روایت کیا ہے:
لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اهل السنة فیوخذ حدیثهم فینظر الی اهل البدع فلا یوخذ حدیثه [9]۔
’’ آغاز میں لوگ راوی سے اسناد کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے پھر جب فتنہ رو نما ہوا تو لوگ کہتے اپنے راویوں کے نام پیش کرو پھر وہ دیکھتا اگر وہ اہل سنت سے ہوتا تو اس کی حدیث لے لیتا اور اگر وہ اہل بدعت سے ہوتا تو ان کی حدیث نہیں لیتا تھا ‘‘
مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت کا کلمہ ابن سیرینؒ کی وفات ۱۱۰ھ سے بھی پہلے مستعمل تھا چنانچہ انہوں نے ما قبل علماء یا اپنے معاصرین کا نکتہ نگاہ ’قالوا ‘سے بیان فرمایا ۔ دوسرا اہل سنت اور اہل حدیث کی اصطلاحات بالمقابل استعمال کی گئی ہیں ،عقائد کی یہ تفریق بعد میں عمل میں بھی ڈھلتی چلی گئی ۔
چنانچہ عقائد و اعمال کے جن مباحث پر قرآن کریم نے کلام نہیں کیا، جن پر رسول اللہ ﷺ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور جن کے متعلق عہد صحابہ سے کچھ منقول نہیں ہوا، انہیں کلامی انداز میں ثابت کرنا یا ان کا دفاع کرنا یا کسی حیثیت سے ان میں مشغول ہونا امام اہل سنت حضرت احمد بن حنبلؒ کے نزدیک بدعت ہے۔
شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں:
وانما کفرالقائل بخلق القرآن وبدع الاخر کان مذهبه رحمه الله، علی ان القرآن اذا لم ینطلق بشئ ولا یروی فی السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم و انقرض عصر الصحابة ولم ینقل احد منهم قولا فلقول فیه بدعة و حدثه [10]-
اہل سنت اوراصحاب تاویل
امام اہل سنت حضرت احمد بن حنبلؒ نے معتزلہ کا خوب مقابلہ کیا تھا چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب معتزلہ کے کیمپ میں سے بعض حضرات نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا اور فلسفی استدلال کی بنا پر اہل سنت کا دفاع اور اہل بدعت کا رد شروع کر دیا مگر علوم شریعت میں ان کی بنیادیں پختہ نہ تھیں یہی باعث ہے کہ گمراہ فرق کے مقابلہ میں انہوں نے بھی تاویل کا ارتکاب کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل سنت میں فلسفی طرز استدلال کا رواج ہو گیا اور تاویل ایک مستقل مذہب بن کر رہ گیا۔
اس مقام پر مسئلہ صفات کے باب میں اہل سنت کے دو گروہ ہوئے ہیں: مفوضین اور مؤولین۔ مفوضین سے مراد وہ حضرات ہیں جو صفات الٰہی کو ان کے ظاہر پر جاری کرتے ہیں اور ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے بلکہ بلا کیف ہی ان پر ایمان لاتے ہیں ۔اہل سنت میں سے حنابلہ اور اہل حدیث بھی اسی کے قائل ہیں۔ مؤولین سے مراد وہ حضرات ہیں جو صفات الٰہی میں کسی قسم کی تاویل کرتے ہیں۔ صفات میں تاویل کرنا جمہور متکلمین کا مذہب ہے، اہل سنت میں سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا شمار بھی اصحاب تاویل یا ارباب کلام میں ہوتا ہے۔
مولانا عطاء اللہ حنیفؒ بھوجیانی رقم فرماتے ہیں:
’’علماء کی وہ جماعت بھی متکلمین کہلاتی ہے، جو عقائد کے مسائل میں امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعریؒ اور علامہ ابو منصور محمد بن محمد الماتریدیؒ کے مکاتب فکر سے متعلق ہیں۔ اکثر شوافع اور مالکی اول الذکر سے اور حنفیہ ثانی الذکر سے منسلک ہیں ، چند مسائل میں دونوں کا اختلاف ہے اور اکثر میں متفق ہیں۔ اہل حدیث ان دونوں سے بہت سے امور میں الگ ہیں ۔ یہ تینوں گروہ اہل السنۃ والجماعۃ ہی ہیں۔‘‘ [11]
اشاعرہ کے بانی ابو الحسن اسماعیل بن علیؒ ہیں۔ آپؒ کا نسب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے جا ملتا ہے۔ آپؒ نے معتزلی استاد ابو علی جبائی سے کسب فیض کیا تھا مگر ان سے الگ ہو کر اہل سنت کا طریقہ اختیار فرمایا۔آپ کے پاس علم حدیث کا ذخیرہ کم تھا، طریق بیان عقلی تھا اور کچھ نہ کچھ اعتزالی اثر باقی رہ گیا تھا۔ جس کے باعث اہل سنت میں بھی علم کلام مقبول ہونا شروع ہوا [12]-
صلاح الدین ایوبی ؒ فروع میں شافعی اور اصول میں اشعری تھے۔ آپ نے مصر میں شیعہ ازم کا خاتمہ کر کے شافعی اشعری طریق رائج کر دیا،جس سے اشعری مذہب نے دیار مصر میں خوب فروغ پایا۔ دوسری جانب بلاد مغرب میں امام غزالیؒ کا شاگرد محمد بن تومرث ہوا ہے، جس کی وفات پر اس کے شاگرد عبد المومن نے بلاد مغرب پر قبضہ کیا اور اشعری طریق کو بزور شائع کر دیا یہی وجہ ہے کہ عقائد کے باب میں شوافع کی اکثریت اشعری واقع ہوئی ہے۔ [13]
ماتریدیہ کے بانی ابو منصور محمدؒ ہیں ۔ جو سمر قند کے ماترید نامی محلہ میں پیدا ہوئے ۔ آپ فقہ کے باب میں حنفی بلکہ تین واسطوں سے امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ آپ نے قاضی ابو بکر جوزجانیؒ سے علم فقہ سیکھا تھا، انہوں نے ابو سلیمان جوزجانیؒ سے پڑھا اور انہوں نے امام محمدؒ سے کسب فیض کیا تھا جو امام ابو حنیفہؒ کے تلمیذ رشید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کی اکثریت عقائد کے باب میں ماتریدیہ واقع ہوئی ہے۔ امام ماتریدیؒ کا طریق بیان او ر صورت استدلال چونکہ فلسفی تھا لہذا آپ نے امام اشعری سے اختلاف کیا اور معتزلہ، قرامطہ اور روافض کا رد کیا اور ایک الگ طریقہ کا بانی قرار پایا۔شافعیہ اور مالکیہ میں سے اکثریت عقائد میں اشعری اور بعض حنبلی ہیں۔ [14]
مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کے باب میں اشاعرہ اور ما تریدیہ کا اختلاف ہے، اختلافی مسائل کی تعداد ایک درجن کے قریب تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف بڑھتا گیا ہے تاہم اس کا دائرہ کار صفات میں تاویل ہی سے متعلق تھا، اشاعرہ کی نسبت ما تریدیہ میں زیادہ تاویل پائی جاتی ہے۔ حنابلہ کا اشاعرہ سے کل چار مسائل میں اختلاف ہے۔ مثلا صفات کا اثبات، رؤیت کا اثبات، تقدیر کا اثبات اور خلق قرآن کا مسئلہ ۔ [15]
مولانا بھوجیانیؒ کے مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اشاعرہ و ماتریدیہ بھی اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں مگر عام اہل حدیث فکر یہ ہے کہ موولین (اشاعرہ اور ماتریدیہ) کو مجموعی حیثیت سے نہ ہی اہل سنت میں شامل کیا جائے گا اورنہ ہی انہیں اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے گا۔
حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ رقم طراز ہیں:
’’ مؤولین کے اہل سنت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، کوئی ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہے اور کوئی داخل۔ لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ نہ علی العموم خارج کہنا ٹھیک ہے اور نہ داخل۔ بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کے حال سے تفتیش کی جائے جیسا معلوم ہو ویسا حکم لگایا جائے اور جس کی بابت تردد ہو، اس کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے {تِلْکَ اُمَّۃٌ قَدْ خَلَتْ لَھَا مَا کَسَبَتْ وَ لَکُمْ مَّا کَسَبْتُمْ} پڑھی جائے۔‘‘ [16]
اہل سنت اور اہل حدیث
اہل حدیث کے خیال میں نسبت رسول اور حجت شرعی کے اعتبار سے حدیث و سنت باہم مترادف ہیں ، اسی لیے اہل حدیث کے نزدیک اضافی مفہوم کے لحاظ سے اہل سنت اور اہل حدیث کا مصداق ایک ہی ہے۔ امام اہل سنت حضرت احمد بن حنبلؒ نے بھی انہیں مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ آپ نے رقم فرمایا:
وهذا مذهب اهل العلم و اصحاب الاثر ، اهل السنة المتمسکین بعروتها المعروفین به المقتدی بهم فیما من لدن اصحاب النبی صلي الله عليه وسلم الی یومنا هذا ۔ وادرکت من علماء الحجاز والشام وغیرهم عليها [17]۔
مذکورہ اقتباس کا مفہوم یہ ہے کہ امام صاحبؒ نے اہل علم اور اہل حدیث کا مذہب بیان کیا ہے جو درحقیقت اہل سنت ہی ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو حدیث وسنت کا کڑا تھامنے والا ہے اور یہی ان کی پہچان ہے۔ یہ لوگ عہد صحابہؓ سے لے کر آج تک حدیث و سنت کے باب میں پیشوا رہے ہیں اور امام صاحبؒ نے علماء حجاز و شام کو اسی عقیدے پر کاربند پایا تھا۔
امام اہل سنتؒ کی وفات کے قریبا ایک صدی بعد معتزلہ سے متاثرہ بعض اہل سنت نے بھی مسئلہ صفات کے اثبات و دفاع میں فلسفی طرز استدلال اختیار کیا جس نے معتزلہ کی بنیادیں اگرچہ کھوکھلی کر دیں تاہم خود اہل سنت میں بھی اصحاب تاویل کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کی شکل میں سامنے آیا۔ ان کے ساتھ ساتھ اہل سنت میں سے ایک گروہ ایسا بھی موجود رہا ہے جس نے قدیم کلامی افکار کی مانند جدید کلامی مباحث سے دامن کشاں رہنا ہی مناسب سمجھا، اس گروہ کو اہل حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث فکر کی روسے اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی حقیقت کا اظہار ہیں۔ مولانا محمدابراہیم میرسیالکوٹیؒ رقم فرماتے ہیں:
’’ان ہر دو نبرد آزما جماعتوں (اشاعرہ وما تریدہ) کے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی چلے آئے ہیں، جنہوں نے اس نئے علم کلام میں بھی حصہ نہ لیاجس طرح انہوں نے معتزلیوں کے علم کلام میں نہ لیا تھا… وہ عقائد و اصول میں بھی روایات صحیحہ کی بنا پر قرآن وحدیث کے بیان اور جماعت صحابہ کے مسلمات پر قائم رہے … یہ محدثین کا گروہ تھا اور ان کے سرخیل، امام اشعریؒ اور امام ما تریدیؒ سے بہت پیشتر امام احمد بن محمد بن حنبلؒ تھے۔‘‘ [18]
امام اشعریؒ کا سن وفات ۳۳۰ہجری اور ا مام ماتریدیؒ کا سن وفات ۳۳۵ ہجری ہے جبکہ امام احمد بن حنبلؒ کا انتقال قریبا ایک صدی پیشتر ۲۴۱ ہجری میں ہو چکا تھا۔
مذکورہ مقدس گروہ نے قرآن کریم میں بھی مخالفین کا مقابلہ کیا اور انہیں مسکت جواب دیا ہے مگر اس میں تکلف یا تصنع کبھی نہیں اٹھایا چنانچہ اہل اسلام کو بھی اپنے عقائد و اصول کے دفاع میں سادہ روی سے ہی کلام کرنا چاہیے اور اس میں عقل و فلسفہ کو دخل نہیں دینا چاہیے یہی باعث ہے کہ وہ اصول وفروع میں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کی اتباع اور عمل صحابہ کی روش پر گامزن رہے ہیں۔ انہی حضرات کو اہل سنت کا نام دیا گیا اور اسی گروہ کو اہل حدیث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:
واما اهل الحدیث والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباع الکتاب والسنة الثابتة عن نبیھم صلي الله عليه وسلم فی الاصول والفروع و ما کان علیه اصحاب رسول اللہ صلي الله عليه وسلم [19]-
اہل سنت کو اس باعث اہل حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حدیث و سنت باہم مترادف ہیں۔ اس تعبیر کا دوسرا معقول سبب یہ بھی ہے کہ حدیث کا لفظ سنت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے جو سنت رسول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو بھی شامل ہے چنانچہ قرآن و حدیث کے عاملین کو اہل حدیث کا نام دیا گیا ہے۔
مولانا محمد یحییٰ گوندلویؒ رقم کرتے ہیں:
’’اہل سنت اور اہل حدیث دونوں ایک ہی نام ہیں۔ اہل حدیث نام رکھنے کی ایک معقول وجہ یہ تھی کہ حدیث کا لفظ قرآن وحدیث پر مشترک بولا جاتا ہے… جس طرح قرآن پر لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح فرمان رسول پربھی لفظ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل حدیث کا معنی ہے: قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا۔‘‘ [20]
اس مقام پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کا لقب اصلاً عقائد و اصول کے باب میں اور اہل حدیث کا نام عموما فقہ و اجتہاد کے باب میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا اہل سنت کا لقب عملی مصداق کے اعتبار سے اہل حدیث کی نسبت زیادہ وسیع ہے جس میں اہل بدعت کے علاوہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر شامل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک عقیدہ کو عمل سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے نہ عمل کو عقیدہ سے الگ رکھا جا سکتا ہے لہذاجس طرح اہل سنت کا دائرہ کار عقائد و اصول کے ساتھ ساتھ فقہ و عمل پر مشتمل ہے، اسی طرح اہل حدیث کا دائرہ کار فقہ و عمل تک محدود یا عقائد و اصول سے خارج نہیں ہے۔
حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ رقم فرماتے ہیں:
’’اصل اہل سنت اہل حدیث ہی ہیں کیونکہ اہل سنت درا صل وہ ہے جو ہر طرح سے سنت سے تعلق رکھے یعنی اصول، فروع، عقائد، احکام میں ہر طرح سنت کے پابندرہے جیسے صحابہ کرامؓ کا طرز عمل تھا۔ جو تھوڑا سا بھی اس طرز عمل سے ہٹا، وہ اصلی اہل سنت کہلانے کا مستحق نہیں ہے … پس ثابت ہوا ہے کہ اصلی اہل سنت اہل حدیث ہیں۔‘‘ [21]
اہل حدیث فکر کی رو سے دعوائے محض کی بنیاد پر کسی شخص کو اہل سنت قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل اپنے دعوی کو کس حد تک ثابت کرتا ہے۔جو شخص اپنے عمل کی بنیاد حدیث و سنت پر رکھے گا، وہی اہل حدیث ہو گا اور اسی کو اہل سنت قرار دیا جائے گا۔ جس کا عمل حدیث و سنت کے خلاف ہو گا، وہ اہل سنت میں نہیں بلکہ اہل بدعت میں شمار ہو گا۔ مولانا عبدالسلام مبارک پوریؒ رقم فرماتے ہیں:
’’اہل حدیث اور اہل سنت دونوں کا مصداق ایک ہے۔ پس جو سنت رسول کا پابند اور جماعت صحابہ کا پیرو ہو، وہی اہل حدیث ہے اور اسی کو اہل السنۃ والجماعۃ کہتے ہیں۔ جو عملاً اہل حدیث ہے، وہی عملاً اہل السنۃ والجماعۃ ہے اور جو زبانی اہل السنۃ والجماعۃ بنتا ہے اور اس کا عمل سنت رسول اور سیرت صحابہؓ اور سبیل صحابہ کے خلاف ہے ، وہ کبھی اہل السنۃ والجماعۃ نہیں ہے۔‘‘[22]
اہل حدیث اور محدثین
اصول حدیث اور اسماء رجال کی کتب میں اہل حدیث کا اطلاق عموماً محدثین پر ہوتا ہے، جس سے بعض حضرات کو مغالطہ ہوا ہے کہ اہل حدیث سے ہمیشہ محدثین ہی مراد ہوتے ہیں اور یہ کوئی مستقل مکتبِ فکر نہیں ہے حالانکہ حدیث و فقہ کی کتب متون وشروح میں اہل حدیث کا اطلاق ایک مکتبِ فکر پر بھی ہوا ہے۔ اس غلط فہمی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ کتب رجال کے اہل حدیث سے کتب فقہ کا اہل حدیث سمجھا گیا وگرنہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں سے جن قدسی نفوس نے فنی اعتبار سے حدیث و سنت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا ہے انہیں کتب رجال کے استعمال میں اہل حدیث قرار دینا درست ہے خواہ وہ اپنے فقہی مکتب ِفکر کی رو سے اہل حدیث نہ بھی ہوں۔
مولانا محمد اسماعیل سلفی نے رقم کیا ہے:
’’ اہل حدیث کا لفظ فن حدیث کے خدام پر بھی بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے اہل حدیث اورمحدث مترادف ہیں۔یہ خدمت تو ظاہر ہے کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر نے انجام دی ہے؛ احناف، شوافع، حنابلہ، موالک، یہ سب حضرات سنت کو حجت مانتے ہیں اس لیے قدرتی بات ہے کہ وہ سنت کی خدمت کریں گے؛ حافظ طحاویؒ، علامہ عینیؒ، شیخ نابغیؒ، علامہ ترکمانیؒ اور حافظ زیلعی ؒکی فنی خدمات کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس معنی سے یہ لوگ اہل حدیث بھی ہیں اور محدث بھی۔ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر سے جن اہل علم نے حدیث کی خدمت بلحاظ فن کی ہے ، وہ اہل حدیث ہیں۔‘‘ [23]
مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر نے فنی ا عتبار سے خدمت حدیث کا فریضہ اپنی اپنی بساط کے مطابق انجام دیا ہے لہذا موالک، احناف، شوافع اور حنابلہ پر بھی فن حدیث کے خدام کی حیثیت سے اہل حدیث کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ خدام حدیث میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مذاہب اربعہ میں سے کسی خاص مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں رہے بلکہ وہ اہل حدیث کے مستقل مکتبہ ٔ فکر میں شمار ہوتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر حدیث کی خدمت کا فرض نبھایا ہے یہی باعث ہے کہ وہ بیک وقت فن حدیث کے خادم ہونے کے علاوہ اس مکتبِ فکر کے ترجمان بھی ہیں یا وہ اہل حدیث مکتبِ فکر کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ فن حدیث کے خدام بھی ہیں بلکہ ابتدائی اہل حدیث اصلا خدام حدیث ہی ہیں۔
مولانا محمد اسماعیل سلفیؒ بیان کرتے ہیں:
’’ابتدائی صدیوں میں اس مکتب فکر کے تمام بزرگ فن حدیث کے خادم تھے اس لیے ان میں خدمت مکتب فکر اورخدمت فن حدیث بیک وقت جمع ہوئے اور عموما جمع ہی رہے لہٰذا دونوں کے لحاظ سے یہ عنوان ان حضرات پر منطبق ہوگیا، اس سے بعض ظاہری حضرات کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ عنوان صرف خدمت فن سے مخصوص ہے حالانکہ یہ مکتب فکر بھی ہے۔‘‘ [24]
دوسرے قرن سے لے کر تیسرے قرن تک کے عہد اختلاف میں ایک جانب عقائدو اصول کے کلامی مباحث کا بازار گرم تھا اور دوسری جانب فقہ و فروع کے میدان میں مذہبی تعصب نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا۔ فلسفی استدلال اور مذہبی جمود کے اس معرکہ آراء دور میں نقلی علوم پر قانع رہنا اور حدیث کو بلا تعصب بالا دستی دینا اہل حدیث ہی کا طرہ امتیاز ہے۔
ڈاکٹر عبدالرشید اظہرؒ فرماتے ہیں:
’’ ان معرکوں کے دور کے بعد اہل حدیث یا محدثین کا لقب ہر حدیث پڑھنے یا پڑھانے یا اس کی شرح لکھنے والے کے لیے نہیں رہا ہے بلکہ کتاب و سنت کے ساتھ مخلصانہ تعلق، ان کی غیر مشروط بالا دستی اور سلف صالحین کا صحیح عقیدہ اہل حدیث کا امتیازی وصف قرار پایا ہے اور ایسے مخلص لوگ ہی اس لقب سے ملقب قرار پائے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی شیوخ ا لحدیث کہلوانے والے اور حدیث کے معروف شارحین اہل حدیث کہلانے کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں۔‘‘ [25]
جو حضرات اہل حدیث کو محدث ہی کے مترادف سمجھتے ہیں اور محدثین کو فقہ و فراست یا فہم و ادراک سے عاری باور کراتے ہیں، ان کا نکتہ نگاہ درست نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اہل حدیث ایک مکتبِ فکرکا نام ہے جس کے خواص کا مشغلہ حدیث کے حفظ و اداء اور نقل و سماع کے ساتھ ساتھ حدیث کا فہم و تدبر اور اس پر عمل و اتباع بھی تھا چنانچہ اہل حدیث کو خاص محدث ہی باور کرانا اور فہم و تدبر یا فکر و دانش کو محدث کے اوصاف سے خارج قرار دینا صحیح نہیں ہے۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ ؒنے رقم کیا ہے:
’’ہمارے نزدیک اہل حدیث سے صرف وہ لوگ مراد نہیں جنہوں نے حدیث کو سنا ، لکھا ا ور روایت کیا بلکہ ان سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو اس کے حفظ، فہم اور معرفت کا ظاہر وباطنی لحاظ سے مستحق ہے اور ظاہری وباطنی لحاظ سے اس کی اتباع کرتا ہے۔‘‘ [26]
جن حضرات نے اہل حدیث کو محدث قرار دیاہے ، انہوں نے محدث کے اوصاف سے فکر و دانش ہی کو خارج نہیں کیا بلکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ عوام اس کے اطلاق سے خارج ہو جائیں گے حالانکہ محدثین کی روایات پر عمل کرنے والا عموامی گروہ ان کے عہد سے آج تک برابر موجود رہا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب کے سب معروف معانی میں محدث نہ ہیں بلکہ وسیع مفہوم کے لحاظ سے اہل حدیث ہیں گویا اہل حدیث فکر کی رو سے اہل حدیث کے مفہوم میں محدثین کرام کے ساتھ ساتھ اہل حدیث عوام بھی شامل ہیں ۔
مولانا زبیر علی زئیؒ رقم طراز ہیں:
’’اہل حدیث ان صحیح العقیدہ محدثین وعوام کا لقب ہے جو بغیر تقلید کے کتاب و سنت پر فہم سلف صالحین کی روشنی میں عمل کرتے ہیں اور ان کے عقائد بھی کتاب و سنت اور اجماع کے بالکل مطابق ہیں۔صرف دو گروہ ہیں حدیث بیان کرنے والے محدثین اور حدیث پر عمل کرنے والے محدثین اور ان کے عوام…‘‘ [27]
اہل حدیث کو محدث ہی قرار دینا اور محدث کو محض حدیث جمع کرنے والا فرد ہی سمجھنا اور حدیث پر عمل کو خارج کر دینا اہل حدیث کے خیال میں درست نہیں ہے چنانچہ جس طرح امام مالکؒ کے اقوال جمع کرنے والا مالکی، امام ابوحنیفہؒ کے فرمودات جمع کرنے والا حنفی، امام شافعیؒ کے فرامین مدون کرنے والا شافعی اور امام احمد بن حنبلؒ کے اقوال مرتب کرنے والا حنبلی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اقوال امام پر وہ عمل پیرا بھی ہوتا ہے اسی طرح اہل حدیث سے مراد رسول اللہﷺ کے اقوال و افعال کا جامع ہی مراد نہیں ہوگا بلکہ وہ احادیث و سنن پر عمل بھی کرے گا۔
مولانا محمد یحییٰ گوندلویؒ رقم فرما ہیں:
’’ ہم اس سلسلہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا حنفی کا معنی یہ ہے کہ جو حنفی ائمہ کے اقوال کو تحریر تو کرے مگر اس پر عمل پیرا نہ ہو؟ کیا اصطلاح میں اسے حنفی کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ حنفی اس کو کہیں گے جو حنفی اقوال پر عمل کرتا ہو۔ اسی طرح اہل حدیث سے مراد بھی وہ لوگ ہیں جو کتاب وسنت پر عمل کرتے ہیں۔‘‘ [28]
اہل حدیث اور شوافع
اہل رائے اور اہل حدیث کے الفاظ ایک دوسرے کی ضد میں استعمال ہوئے ہیں۔ اہل سنت کے فقہی مکاتب فکر میں سے احناف کو عموما اہل رائے قرار دیا جاتا ہے جبکہ موالک، شوافع اور حنابلہ کے مکاتب فکر اہل حدیث میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اہل حدیث فکر کی روسے موالک، شوافع اور حنابلہ کو مطلقا اہل حدیث سمجھنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ مستقل طور پر الگ الگ مکاتب ِ فکر ہیں۔
مولانا محمد اسماعیل سلفیؒ نے رقم فرماتے ہیں:
’’شوافع، موالک اور حنابلہ کو علی الاطلاق اہل حدیث سمجھنا بالکل سطحی نظریہ ہے جو جامد تقلید کے شیوع اور عروج کے بعد وضع کیا گیا ورنہ اہل حدیث یا اصحاب حدیث ایک ایسا مکتب فکر ہے جس نے تدوین سنت کے علاوہ دین کے ہر محاذ پر اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کیے ہیں۔‘‘ [29]
مذکورہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے اہل حدیث ایک مستقل مکتبِ فکر ہیں ا ور انہیں موالک یا شوافع یا حنابلہ سے مطلقا نسبت دینا درست نہیں ہے۔ احکام و مسائل کے باب میں اہل حدیث کا نکتہ نگاہ عموماً شوافع یا حنابلہ کے مترادف یا ان کے قریب تر ہوتا ہے جس سے بعض حضرات کو مغالطہ ہوا کہ شوافع ہی کا دوسرا نام اہل حدیث ہے اور اہل حدیث کوئی مستقل مکتبِ فکر نہیں ہے حالانکہ کتب فقہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد مسائل میں شوافع کے ساتھ ساتھ اہل حدیث کا موقف الگ سے بیان ہوا ہے جس کی چند امثلہ درج ذیل ہیں:
۱۔ سوال یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہو گا یا نہیں؟ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور دوبارہ وضو نہیں کیا جائے گا۔ جمہور علماء کرام کے برخلاف ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اہل حدیث بھی اس کے قائل ہیں۔
امام نوویؒ فرماتے ہیں:
وذهب الی انتقاض وضوء به احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه و یحی بن یحی و ابو بکر بن المنذر وابن خزیمة واختاره الحافظ ابو بکر البيهقي وحکی عن اصحاب الحدیث مطلقا [30]-
’’احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ ، یحیی بن یحیی ، ابو بکر بن منذر اور ابن خزیمۃ کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حافظ ابو بکر بیہقی نے بھی اسے اختیار کیاہے۔ اہل حدیث کا مطلقا یہی موقف نقل کیا گیا ہے۔‘‘
۲۔ تیمم کے باب میں ایک سوال یہ ہے کہ کتنے ہاتھ پر مسح کیا جائے گا؟ جمہور علماء کے نزدیک تیمم میں کہنیوں تک مسح کرنا لازم ہے ۔ اس کے برخلاف اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ کف تک کا مسح کیا جائے گا بس!
علامہ ابن رشدؒ رقم کرتے ہیں:
والقول الثانی، ان الفرض هو مسح الکف فقط وبه قال اهل الظاهر و اهل الحدیث۔ [31]
’’دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ہتھیلی کا مسح فرض ہے۔ یہ اہل ظاہر اور اہل حدیث کا موقف ہے۔‘‘
مذکورہ امثلہ اہل حدیث کے اس دعوی کا بین ثبوت ہیں کہ اہل حدیث کا مکتب ِفکر شوافع سے الگ ہے وگرنہ انہیں الگ سے بیان نہ کیا جاتا۔ حنابلہ سے اہل حدیث کے تعلق کا بھی یہی حال ہے کہ اہل حدیث اکثر مسائل میں حنابلہ کے قریب تر ہونے کے باوجود متعدد مسائل میں ان سے الگ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کا مکتبِ فکر کبھی جمود و تعصب کا شکار نہیں ہوا۔ اہل حدیث اگرچہ تمام مکاتب فکر سے وابستہ بھی رہے ہیں تاہم ان میں مدغم نہیں ہوئے بلکہ اپنا تشخص برقرار رکھا ہے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفیؒ رقم طراز ہیں:
’’اہل حدیث حضرات پر چونکہ فقہی جمود کا وقت کبھی نہیں آیا، خدمت فن اور حریت فکر ان میں عموما جمع رہی اور فقہی مسائل میں ان کا تعلق تمام مشہور مکاتب فکر سے برابر رہا ہے۔ یہ حضرات سب کے ساتھ ہونے کے باجود کبھی کسی کے دامن سے وابستہ نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کا صحیح عنوان اہل حدیث یا اصحاب الحدیث ہی ہو سکتا ہے جس کا تذکرہ قریبا دوسری صدی کے ابتداء ہی سے شروع ہوگیا۔ رجال کی کتابوں سے معلوم ہوتاہے کہ اولاً یہی مکتب فکر تھا۔‘‘ [32]
اہل حدیث مکتبِ فکر
امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ ، امام شافعیؒ وغیرہم کے عہد سے لے کر آج تک ان کے اصحاب کے ساتھ ساتھ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود رہا ہے، جو اپنی الگ اور مستقل فقہی آراء اور کلامی نظریا ت رکھتا تھا۔ وہ کسی اہل علم کی تقلید نہیں کرتا تھا بلکہ قرآن و سنت کی واضح نصوص پر عمل کرتاتھا۔اس زمانے سے لے کر آج تک اہل علم نے اس گروہ کو کبھی اہل الحدیث، کبھی اصحاب الحدیث، کبھی فقہاء الحدیث، کبھی فقہاء اہل الحدیث، کبھی فقہاء المحدثین، کبھی فقہاء اہل الاثر اور کبھی صرف محدثین کے نام سے موسوم کیا ہے اور ان کی فقہی آراء کو ایک مستقل مذہب کے طور پر بیان کیا ہے۔مفتی رشید احمد لدھیانویؒ رقم فرماتے ہیں:
’’تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق کےفروعی اور جزوی مسائل حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر پانچ مکاتب فکر قائم ہو گئے یعنی مذاہب اربعہ اور اہل حدیث۔ اس زمانے سے لے کر آج تک انہی پانچ طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا ہے۔‘‘ [33]
مذکورہ اقتباس میں حضرت لدھیانویؒ نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے ، وہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے چنانچہ اہل حدیث کو فن حدیث کی خدمت تک ہی محدود رکھنا اور اسے ایک مستقل مکتب ِفکر نہ سمجھنا مقالہ نگار کے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ امام شہرستانیؒ نے اہل رائے اور اہل حدیث کے اختلاف کو اجتہاد کا اور علامہ ابن خلدونؒ نے فقہ کا باب بتایا ہے چنانچہ اہل حدیث کو خادم فن حدیث ہی سمجھنا اور فقہ و اجتہاد سے عاری قرار دینا اپنے خانہ ساز فلسفہ کی بنا پر تاریخ جھٹلانے کے مترادف ہے ۔
چنانچہ مولانا محمد حسین بٹالویؒ رقم طراز ہیں:
’’جس مسئلہ اعتقادیہ میں صریح سنت نبوی کا علم نہ ہو اس مسئلے میں اہل حدیث کا متمسک آثار سلفیہ ہوتے ہیں اور وہی مذہب اہل حدیث کہلاتاہے جس کو متون اور شروح کتب حدیث و فقہ میں اہل حدیث سے منسوب کیا کیا گیا ہے۔‘‘ [34]
دعائے قنوت قبل از رکوع ہے یا بعد از رکوع؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اہل حدیث کے متعلق فرماتے ہیں :
واما القنوت فالناس فیه طرفان و وسط، منهم من لا یری القنوت الا قبل الرکوع ومنهم من لا یراه الا بعده، واما فقهاء اهل الحدیث کأحمد وغیره فیجوزون کلا الامرین لمجیء السنة الصحيحة بهما [35]-
’’قنوت کے باب میں فقہا کی دو انتہائی اور درمیانی آراء ہیں: بعض کے خیال میں قنوت رکوع سے قبل اور بعض کے نزدیک رکوع کے بعد ہے مگر فقہائے اہل حدیث مثلاً امام احمدؒ وغیرہ دونوں ہی کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے متعلق صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں۔‘‘
حق مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ اس حوالے سے حافظ ابن حجرؒ نے اہل حدیث کا مذہب رقم فرمایا ہے:
وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته أقل من درهم وبه قال... ابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء أصحاب الحديث وبن وهب من المالكية [36] -
’’مذکورہ تمام فقہاء نے کسی منفعت بخش چیز مثلا جوتے یا تسمے کا حق مہر بننا بھی جائز قرار دیا ہے جس پر زوجین یا منکوحہ کا سرپرست راضی ہو جائیں۔ ابن ابی لیلیٰ، شافعی، داؤد، فقہائے اہل حدیث اور مالکیہ میں سے ابن وہب کا یہی موقف ہے۔‘‘
قنوت نازلہ کا مشروع ہو نا اہل حدیث کے نزدیک مسلم ہے، جس کی بابت شرح ہدایہ میں لکھا ہے:
’وبه قال جماعة من اہل الحدیث [37]۔
صفات الہیہ کے باب میں اہل حدیث کا مذہب بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:
واستطال هؤلاء الخائضون علی معشر اهل الحدیث وسموهم مجسمة ومشبهة[38]۔
قلتین کے باب میں امام ابن حزمؒ نے اہل حدیث کا مذہب بیان کر کے فرمایا ہے:
وبه قال اسحاق و ابو عبیدة وجماعة من اهل الحدیث منهم ابن خزيمة [39]
علامہ ابن عابدین حنفی نے اہل حدیث کے ساتھ نکاح کے جواز یا عدم جواز کے متعلق ایک واقعہ کی بابت ذکر کرتے ہیں :
’’ان رجلا من اصحاب ابی حنیفة خطب الی رجل من اصحاب الحدیث۔[40]‘‘
’’بلا شبہ ایک حنفی شخص نے ایک اہل حدیث کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا ۔‘‘
نماز مغرب سے قبل دو رکعت نفل کے متعلق امام ابن حجر عسقلانیؒ نے اہل حدیث کا مذہب رقم کیاہے:
والی استحبابها ذهب احمد و اسحاق و اصحاب الحدیث -
خبر واحدکے متعلق اہل حدیث کا موقف بیان کرتے ہوئے حاشیہ نور الانوار میں رقم ہے:
و هذا هو مذهب بعض اهل الحدیث۔‘‘[41]
حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اہل حدیث کو اہل ظاہر سے الگ کرکے بیان فرمایا ہے:
فهذه طريقة المحققین من فقهاء المحدثین و قلیل ماهم وهم غیر الظاهرية من اهل الحدیث الذین لا یقولون بالقیاس والاجماع[42]-
’’فقہائے محدثین میں سے محققین کا طریقہ یہی ہے اگرچہ وہ قلیل ہیں اہل حدیث اہل ظاہر کے علاوہ ہیں۔ اہل ظاہر اجماع و قیاس کے قائل نہ ہیں۔‘‘
مذکورہ امثلہ سے واضح ہوتا ہے کہ اہل علم نے مذاہب اربعہ کے بانی ائمہ کرام اور دیگر فقہاء کرام کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کا بھی ذکر کیا ہے ، جسے انہوں نے فقہائے حدیث کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ان کا اپنا ایک مکتبِ فکر تھا اور وہ کسی امام خاص کے مقلد نہ تھے وگرنہ ان کی آراء کو الگ ذکر کرنے کی قطعا کوئی ضرورت نہ تھی، گویا ابتدائی زمانہ ہی سے اہل حدیث کا مکتبِ فکر بھی موجود رہا ہے اور متاخرین اہل حدیث نے بھی اپنے مذہب کو انہی کے موقف سے مستند قرار دیا ہے ۔
ضمیمہ: اہل حدیث اور سلفی مکتب فکرکے امتیازات مکتب اہل حدیث ’شریعت محمدیہ‘ کا ایک نمائندہ ’مدرسۂ فکر ‘ہے ، جو دورِ تقلید سے قبل خیر القرون میں مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کی قیادت میں نمایاں رہا جس کے مقابل مشہور محدث اور فقیہ ابراہیم نخعی اہل الرائے سے معروف ہوئے ۔ اس وقت دونوں مکاتب فکر کے ترجمان اہل علم تھے ۔برصغیر پاک و ہند میں اکبر کے دینِ الٰہی کے خلاف مجدّد الف ثانی (شیخ احمد سرہندی ) نے جو عَلم توحید بلند کیا تو اس میں ’ شریعت ‘ کو ’تصوف ‘ پر حاکم بتایا گیا ۔ بعد ازاں شاہ ولی اللہ دھلوی تقلیدی جمود کے خلاف کتاب و سنت کی حدود میں اجتہادی وسعتوں کو نکھارتے رہے، جو ان کے اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور شاہ محمد اسحاق دھلوی کی اجتہادی ؍ جہادی مساعی کے علاوہ غزوِ فکری کی صورت میں پھیلتا رہا ۔ 1857ء کی جنگ آزادی کی ظاہری ناکامی پر علمائے صادق پور وغیرہ پر سخت سامراجی تشدد کے سبب قتال نے غزوِ فکری کی صورت اختیار کرلی ۔ سیاسی تحریکوں کے دوران تحریک آزادیٔ فکر بھی عوام کے ذہنوں میں پروان چڑھتی رہی جو مولانا محمد حسین بٹالوی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کی سرپرستی میں عوامی تحریک کا رنگ اختیار کرگئی۔ اس کا نام ’’تحریک اہل حدیث ‘‘ رکھ دیا گیا ۔اب مکتب اہل حدیث اور تحریک اہل حدیث اسی کے دو رُخ ہیں ۔ مکتب اہل حدیث خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب کی وہابی تحریک سے ہم آہنگ ہو کر ’ سلفی ‘ لقب کو پسند کرتا ہے جبکہ عوامی تحریک اہل حدیث ایک پائیدار گروپ ہے ۔جس کا مستقبل کیا ہو ؟ لمحۂ فکریہ ہے !یہ مسئلہ علماء کے غور و فکر کا متقاضی ہے کہ تحریک اہل حدیث صرف تقلیدی جمود کے خلاف ہے یا چند فروعی مسائل کے علاوہ کوئی ٹھوس اصولی بنیادیں بھی رکھتی ہے جس پر ’ تحریک اہل حدیث‘ کا مستقبل استوار ہونا چاہیے ۔درج بالا نکات پرغور و فکرکے لیے اہل علم و قلم کو ’علمی مذاکرہ‘ میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے ۔ (محدث) |
[1] صحیح البخاری ، کتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبی :۳۴۵۰
[2] صحیح البخاری ، کتاب الأنبیاء ، باب ما ذکر عن بنی إسرائیل : ۳۲۶۹
[3] تاریخ اہل حدیث، ص ۲۴
[4] الشهر ستانی، الملل والنحل ۱؍۴۸
[5] ہفت روزہ، اہل حدیث، امرت سر، ۲۸ فروری ۱۹۱۹ء، ص۱۹
[6] سنن أبی داود، کتاب السنة باب فی لزوم السنة،( ۴؍۲۰۰) رقم الحدیث۴۶۰۷
[7] اہل سنت کی تعریف از محدث روپڑی ، ص ۶۵، ۶۶
[8] ہفت روزہ، اہل حدیث، امرت سر، ۲مئی ۱۹۱۹ء، ص۲۰
[9] مقدمة صحیح مسلم،۱۱
[10] غنية الطالبین، مترجم، نعمانی کتب خانہ لاہور
[11] حاشیه، اصول تفسیر لابن تیمیه ، مترجم (المکتبة السلفية، لاہور، جون ۱۹۸۲ء) ص : ۵۹
[12] منهاج السنه ، ۳؍۲۰۵
[13] الاشاعرة فی میزان اهل السنة، المبرة الخیرة لعلوم القرآن والسنة، دولة الکویت، ۱۴۲۸ھـ
[14] الماتریدية دراسة و تقویما، دارالعاصمة، للنشروالتوزیع، النشرة الاولی، ۱۴۱۳ھـ
[15] کتاب الاسماء والصفات للبیهقی ، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان،
[16] اہل حدیث کی تعریف، ۴۸
[17] عقیدۃ اہل السنۃ، ۳، طبع دہلی، ہند، س ن
[18] تاریخ اہل حدیث،۶۲
[19] منهاج السنة ، ۲؍۱۰۳
[20] عقیدہ اهل حدیث (مکتبہ اسلامیہ، لاہور اکتوبر ۲۰۱۰ء) ، ۳۹- ۴۱
[21] اہل حدیث کی تعریف، ۷۲
[22] ہفت روزہ، اہل حدیث، امرت سر، ص ۸، ۳۰ جنوری ۱۹۲۰ء
[23] مقالات حدیث، ۵۲۶، ام القری پبلیکیشنز، گوجرانوالہ، فروری ۲۰۰۹ء
[24] مقالات حدیث، ۵۲۸
[25] مقالات تربیت، ۴۶، دار التربیۃ للنشر والتالیف، فیصل آباد، نومبر ۲۰۰۹ء
[26] مجموع الفتاوی ابن تیمیه، ۴؍۹۵، دار العربيه، للطباعة والنشروالتوزیع، بیروت، لبنان
[27] تحقیقی، اصلاحی اور علمی مقالات،۱۷۲
[28] عقیدہ اہل حدیث، ۵۷
[29] مقالات حدیث، ۵۳۰
[30] شرح مسلم، ۴؍۴۹
[31] بداية المجتهد ونهاية المقتصد،۱؍۵۰، دارالتوفیق للطباعة جامعة الازهر، مصر ، ۱۴۰۳ھـ
[32] مقالات حدیث، ۵۲۸
[33] احسن الفتاوی، ۱؍۳۱۶
[34] تاریخ اہل حدیث از ڈاکٹر بہاؤ الدین : ۱؍۲۰۵
[35] مجموع الفتاوی، ۲۳؍۱۰۰
[36] فتح الباری، ۹؍۲۰۹
[37] کمال الدین سیواسی، شرح فتح القدیر،۱؍۴۳۴
[38] حجة الله البالغة، ۱؍۶۴
[39] المحلی، ادارة الطباعة المنیریه، دمشق، طبع اول ۱۳۴۹ھـ
[40] ردالمحتار شرح الدر المختار: 3؍۳۹۳
[41] نور الانوار مع شرح قمر الاقمار :
[42] عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد :71