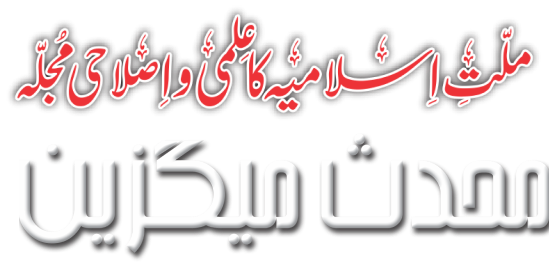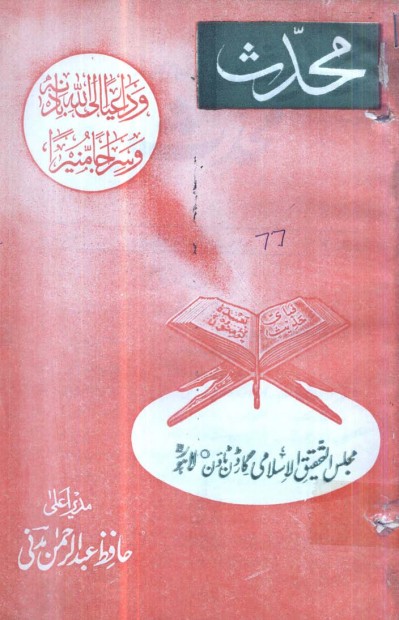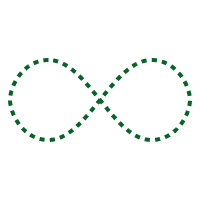شِعرُ العرب
عربی شاعری پر کچھ لکھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مطلق شاعری کے متعلق ضروری امور درج کردیئے جائیں۔
شاعری پر سب سے پہلی تالیف: غالباً ارسطو ہی نے سب سے پہلے ''شاعری'' پر ایک کتاب ''بوطیقا'' تصنیف کی ہے۔جس کی تلخیص ابن رُشد نے کی ہے اور اس کے کچھ حصے شیخو لویس نے اپنی کتاب علم الادب میں شامل کیے ہیں۔
تعریف: عام طو رپر شاعری کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسے کلام موزوں کا نام ہے جو بالارادۃ موزوں کیا گیا ہو۔ ابن رشیق نے بھی اپنی کتاب ''العمدہ'' میں تعریف کی تائید کی ہے لیکن اکثر ادباء وزن اور قافیہ کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔
جان اسٹورٹ مل کہتا ہے کہ جذبات کو برانگیختہ کرنے والی چیز شاعری ہے۔ اس کے خیال کے مطابق تصویر تقریر و وعظ شعر میں داخل ہوجاتے ہیں، اس لیے شاعری کو اس طرح محدود کیاجاتا ہے کہ شاعری میں شاعر صرف اپنے آپ سے خطب کرتا ہے اور تقریر وعظ وغیرہ میں مخاطب حاضرین ہوتے ہیں۔
ارسطو کے نزدیک شاعری ایک قسم کی مصوری یا نقالی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مصور صرف مادی اشیاء کی تصویر کھینچتا ہے اور شاعر جذبات و احساسات کی تصویر پیش کرتا ہے۔
مولوی حمیدالدین صاحب نے جمہرۃ البلاغۃ میں لکھا ہے کہ شاعر کے لفظی معنی ذی شعور اور احساسات رکھنے والے کے ہیں۔ مختلف جذبات کی وجہ سے انسان مختلف حرکتیں کرتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے او رکبھی موزوں الفاظ سےاپنے تاثرات ظاہرکرتا ہے۔
شاعری اور فلسفہ کا فرق: افلاطون نے ''فلسفی'' کوشاعر کہا ہے، افلاطون فیلسوف ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا فلسفیانہ نظام خود ایک آرٹ ہے ۔ بلکہ وہ آرٹ سے بھی ماوراء ہے اور شاعر ایک تکوینی ذہن رکھتا ہے ، وہ فطرت اور واقعات دہر سے متاثر ہوکر دل کی بھڑاس نکالنا شروع کردیتا ہے وہ کسی کے سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ خود سمجھ کر شیخ اٹھتا ہے ؎
پھوٹ پڑتے ہیں تماشا اس چمن کا دیکھ کر
نالہ بے اختیار، بلبل نالاں ہیں ہم
حقیقی او ربلند پایہ شاعر فیلسوف ہوتاہے یوں تو بقول شوپن ہائر (Shopen haur)کے ہر انسان مابعد الطبیعاتی حیوان ہے لیکن نہ ہر انسان شاعر ہے اور نہ ہر شاعر فلسفی۔
وہ شاعر جو نظم نگاری ہی کی حد تک محدود نہیں بلکہ جس پر اسرار کائنات خود بخود منکسف ہوتے ہیں جو بنایا نہیں جاتا بلکہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اندر کائنات کےمتعلق حقیقت بینی کی وہی صفت رکھتا ہے جوایک فلسفی کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹے فی سن نے ایک پھول دیکھ کر کہا تھا کہ اگر کوئی اس کو پورا طرح سمجھ لے تو وہ خدا، اپنی ذات او رکائنات کی ماہیت سے واقف ہوجائے گا۔ ''ہر ورق دفتر یست معرفت کردگار'' ابونواس کہتا ہے کہ وکل شئ لہ ایۃ۔ تدل علی انہ واحد۔
فلسفہ دراصل ہمہ گیر توجیہ یا دوسرے الفاظ میں حسب امکان بشری حقائق کائنات کے معلوم کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ فلسفی انتہائی علل و اسباب معلوم کرنے کرتا ہے اس کو ایک مسلسل جستجو رہتی ہے ۔ وہ عالم طبعی (مادیات ) حیات ، ذہن ، سماج، حکمت اور اقدار کے وسیع موضوع میں کام کرتا ہے ۔ یقیناً فیلسوف کا کام بہ نسبت شاعر کے بہت زیادہ ہے۔ (اقبال)
جہاں داری سے ہے مشکل ترکار جہاں بینی
جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا
فلسفی حقائق کو خشک پیرایہ میں بیان کرتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر حقائق کو ایسے دلچسپ او رجذبات کے ابھارنے والے پیرایہ میں بیان کرنا ہو تو شاعری کی ضرورت ہوتی ہے۔
شاعری کے امتیازات
1 ۔ شاعر کسی کے سمجھانے کے لیے نہیں چلاتا بلکہ خود سمجھ کر چیختا ہے۔
2۔ شاعر ، فلسفی یا مؤرخ کی طرح چیز کے ہر پہلو کو دیکھ کر مستقل رائے قائم کرنے کا ذمہ دار نہیں اس لیے ممکن ہے کہ شاعر ایک چیز کی تعریف کرے اور اس کی مذمت بھی او رممکن ہے کہ وہ ایک اچھی چیز کی مذمت کرے اور بُری چیز کی تعریف۔ الغرض شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز کو من حیث الحقیقہً حسب الواقع پیش کرے۔
''بخار'' کی حقیقت طبیب کے نزدیک عفونتی یاجراثیمی اثر کا نتیجہ ہے جس سے بدن کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور لرزہ پھریری شرو ع ہوتے ہیں اور جب اس کی نوبت ختم ہوجاتی ہے تو پسینہ آتا ہے ۔ لیکن شاعر و متنبی کہتا ہے۔
وزائرتي کان بھا حیاء ........ فلیس تزور إلافي الظلام
بذلت لھا المطارف والحشایا ........ فعا فتھا و باتت في عظامي
یضی الجلد عن نفسي و عنھا ........ فتو سعه بأنواع أسقام
اراقب وقتھا من غیر شوق ........ مراقيه المشوق المستھام
ویصدق وعدھا و الصدق شر ........ إذا ألقاك في الکوب العظام
أبنت الدھر عندي کلبنت ........ فکیف و صلت أنت من الزھام
(ترجمہ) ''ایک میری ملاقات کرن ےوالی ہے جو بوجہ حیا وشرم کے صرف شب ہی کو تشریف لاتی ہے۔ اس کے لیے میں تو شک (چادر وغیرہ) پیش کرتا ہوں تو وہ اس کو ناپسند کرتی ہے اور میری ہڈیوں میں شب گزارتی میری جلد میں میری جان او راس ملاقاتی کے لیے گنجائش نہیں ہے اس لیے وہ قسم قسم کی بیماریوں سے میرے جسم کو گھلاتی اور جلد کو وسیع کرتی ہے مجھے اس کے وقت کا عاشق مشتاق کی طرح انتظار رہتا ہے لیکن رغبت سے نہیں وہ وعدہ کی سچی ہے او رایسی سچائی سے توبہ ہی بھلی جس سے آدمی مصیبتوں میں مبتلا ہوجائے۔ اے زمانہ کی صاحبسادی زمانہ کی تمام بیٹیاں (مصائب) میرے پاس موجود ہیں بلکہ مجھے تعجب ہے ان بیٹیوں کے اژدھام میں سے آپ کو میرے تک رسائی کا راستہ کیسے مل گیا۔''
اگر ایک آدمی کو قتل کیا یا سولی پر لٹکایا دیاجائے تو یہ منظر کس قد ربھیانک ہوگا لیکن ابوالحسن انباری المتوفی 328ھ آج سے ایک ہزار سال پہلے وزیر ابوطاہر کا مرثیہ کہتا ہے جس کو عضد الدولہ نے قتل کروا کے سولی کا حکم دیا تھا او راس کریہہ منظر کی تعریف کرتا ہے۔کہتے ہیں کہ اس قیصدہ کو سن کر عضدالدولہ رشک کرنے لگا کہ کاشی مجھے سولی دی جاتی اور یہ مرثیہ میری ہی شان میں ہوتا۔
علو في الحیاة وفي الممات ........ لحق أنت إحدی المعجزات
کان الناس حولك إذا قاموا ........ وفود نداك أیام الصلات
کأنك قائم فیھم خطیبا ........ وکلھم قیام للصلوة
مددت یدیك نحوھم احتفاء ........ کمدهم إلیھم بالھبات
ولما ضاق بطن الأرض عن أن........ یضم علاك من بعد الممات
أصادوا لجو قبرك و استعاضو ........ عن الاکفان ثوب الأفیات
لعظمك في النفوس تبیت ترعی ........ بحراس وحفاظ ثقات
ولو قد حولك النیران قدما ........ کذلك کنت أیاما الحیاة
رکبت مطیة من قبل زید ........ علاھا في السنین الماضیات
وتلك قضیة فیھا تأس ........تباعد عنك تعییر العداة
ولم أرقبل جذعك قبل جدعا ........ تمکن من عناق المکومات
أسات علی النوائب فاستثارت ........ فأنت قتیل ثأرالنائبات
علیك تحیة الرحمٰن تتری ........ برحمات غواد رائحات
(ترجمہ) ''زندگی میں بھی بلندی او رمرنے کے بعد بھی بلند ، واقعی تو ایک زبردست معجزہ ہے۔ گویا کہ لوگ تیرے اطراف تیرے عطیوں کے حاصل کرنے والی جماعتیں جو ایام تقسیم میں جمع ہوتی تھی۔ ایسامعلوم ہوتا ہےکہ تو کھڑے ہوکر خطبہ پڑھ رہا ہے او رسب لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو نے ان کی طرف اپنے ہاتھ ایسے پھیلائے ہیں جیسے کہ بخشش دیتے وقت پھیلاتا تھا۔ چونکہ آغوش زمین تیری وسیع بلندیوں کے لیے تنگ ہے تیرے لیے فضا کو قبر بنانا پڑا او ربجائے کپڑوں کے چلنے والی بیکراں ہواؤں کو کفن بنایا گیا ۔ تیرے اطراف تیری شان و شوکت کے خاطر ایک محافظین کی معتبر جماعت معین کی گئی او رجس طرح ایام زندگی میں مہمان نوازی کی آگ جلائی جاتی تھی، تیرے اطراف آج بھی آگ جلائی گئی ہے، تو اس سواری پر سوار ہوا جس پر گزشتہ سالوں میں حضرت زید بن علی جیسی مقدس ہستی بلند ہوچکی ہے او ریہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے بعد نکتہ چینیوں کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہتا ، میں نے آج سے پہلے کسی درخت کے تنے کو مجسم شرافتوں سے معانقہ کرتے نہیں دیکھا۔ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور رحمت کے صبح و شام برسنے والے ابر برستے رہیں۔''
زمین کا زلزلہ یابھونچال کتنی خوفناک چیز ہوا کرتی ہے ۔ لیکن شاعر کے تخیل میں اپنے ممدوح کے عدل و انصاف سے طرب میں آکر ملک کی سرزمین کا سرڈھننے یا رقص کرنے کا نام ہے۔
شاعر کہتا ہے:
ما زلزلت مصر من کید یرادبھا ........ وإنما رقصت من عدله طربا
چاند کا ابر میں چھپ کر آنکھوں سے اوجھل ہوجانا معمولی بات ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ماہ کامل میرے ممدوح کے چہرہ کی آن بان چمک دمک دیکھ کر اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کو ابر میں جاکر منہ چھپانا پڑا۔
أری بدر السماء یلوح حینا ........ و یبدوثم یلتحف السحایا
وذاك لأنه لما تبدی ........ وأبصر وجھك استحیا وغابا
3۔ شاعر بادشاہ کانام لےکر پکار سکتا ہے اس کو اس کی ماں کی طرف منسوب کرتا ہے جو دوسرے مواقع میں خلاف تہذیب س سمجھا جائے گا۔
4۔ نظم کے مقبول مشہور محفوظ ہونے کا جتنا امکان ہے اتنا نثر کے لیے نہیں۔ چنانچہ یہ مسلم ہے کہ بہ نسبت ''نظم'' کے قدماء عرب نے نثر بہت کہی ہے لیکن نثر کے دس قطعات بھی محفوظ نہ ہوسکے۔ اور نظم سے شاید دس نظمیں بھی ضائع نہ ہوسکیں۔
5۔آرٹ کی سات قسموں یعنی موسیقی، شاعری، سنگ تراشی،رقص، معماری، مصوری،خوشنویسی کی طرف یوں ہی طبیعت کا میلان زیادہ ہوتا ہے او رہ رایک میں دلکشی پائی اتی ہے او رموسیقی جو سب سے زیادہ محرک اور جذبات کو ابھارنے والی شے ہے او رجس سے روح نہایت مست ہوجاتی ہے، کلام موزوں کا ایک ضروری جز ہے اس لیے فن شاعری کو جو فضیلت اور اہمیت و مقبولیت حاصل ہے ظاہر ہے۔
6۔ شعراء کے ہاتھ میں قوم کی باگ ہوتی ہے، جدھر چاہتے ہیں قوم کو جھونک سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں رجز کے چار مصرعے جو کام کرسکتے ہیں جنگی باجے نہیں کرسکتے۔ ذہنیت کے بدلنے یا جدید ذہنیت کی تخلیق میں شاعری کو جو دخل ہے وہ دوسری کسی چیز کو بھی نہیں۔ استقلال و ثبات کی تعلیم کتابوں سے اس قدر نہیں ہوسکتی، جتنی شاعری سے ہوسکتی ہے۔
7۔ شاعر کے لیے فخریہ کلام جائز ہے۔
8۔ شاعر سب کچھ کہہ جاتا ہے لیکن قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس کے قول و عمل میں توافق لازمی نہیں چنانچہ ایک شاعر رندمشرب پرہیزگاروں کی سوسائٹی کا ایسا صحیح نقشہ پیش کرتا ہے کہ خود پرہیزگار بھی پیش نہیں کرسکتا او رایک متقی پرہیز گار شاعر جس نے تقویٰ اور ورع کے حلقہ سے باہر قدم نہیں رکھا رند اور اوباشوں کا ایسا چربا اتار سکتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر کسی میخانہ کا زبردست پیرمغاں ہے۔
9۔ شاعری سے بعض گمنام شخصیتوں کو وہ شہرت حاصل ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام بلند ہوگیا اوربعض بلند ہستیوں یا قبیلوں کو شاعر نے اتنا گرایا کہ ہمیشہ کے لیے ان کانام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ شماخ بن ضرار نے عرابتہ کی شان میں یہ شعرکہا:
إذا مارأیته رفعت لمجل ........ تلقا ھا عرابة بالیمین
(ترجمہ )'' عظمت و بزرگی کا کوئی نشان بلندکیا جاتا ہے تو عرابہ اس نشان کو فوراً اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔''
عرابہ کا نام اس شعر کی وجہ سے عرب میںمشہور ہوگیا اور آج تک یہ مصرع ضرب المثل ہے۔
عرب میں محلق ایک گمنام شخص تھا لوگ ان کے ساتھ صمدھیانہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے اعشی نے میلہ عکاظ میں ایک قصیدہ پڑھا۔ تمہید کے بعد یہ شعر تھے۔
لعمري لقد لاحت عيون كثيرة *** إلى ضوء نار في يفاع تحرق
تشب لمقرورين يصطليانها *** وبات على النار الندى والمحلق
(ترجمہ) ''میری زندگی کی قسم اس آگ کی طرف جو بلند مقام میں جلائی جاتی ہے بہت سی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دوسردی زدہ اشخاص کے لیے یہ جلائی گئی ہے جو اس سے مستفید ہوئے ہیں اور آگ کے پاس محلق اور ندیٰ شب گزارتے رہے۔'' اس کے بعد محلق کی بیٹیاں شرفاء عرب کے مشہور افراد کے ساتھ بیاہی گئیں۔
نمیر ایک مشہور قبیلہ تھا، اس قبیلہ کے افراد بڑے ناز سے اپنا نمیری ہونا بیان کرتے تھے۔ غرور کے لہجہ میں بھاری آواز سے نمیر کا نام لیتے تھے اس قبیلہ کے ایک فرد سے جریر کو رنجش ہوگئی۔ گھر آکر اپنے فرزند سےکہا ،آج چراغ میں تیل زیادہ رکھنا اس قبیلہ کی ہجو کہنا ہے۔ ہجو شروع کی جب یہ شعر قلم سے نکلا۔
فغضّ الطّرف إنك من نميرٍ ... فلا كعباً بلغت ولاكلابا
جریر اُچھل پڑا او رکہا ''والله أخزتیه آخر الدھر'' ''بخدا اس شخص کو ہمیشہ کے لیے رسوا کردیا۔'' اب یہ نوبت پہنچی کہ اگر کسی نمیری سے اس کا خاندان دریافت کیا جائے تو نمیر کا نامنہ لیتا۔ بلکہ وہ چارپشت چھوڑ کر اوپر کی پشتوں کا نام بتاتا۔ شاعر کےمقبول ہونے پر قبائل عرب میں شاندار دعوتیں اور جشن ہوتے تھے کیونکہ شاعر سے ان کی عزت کی حفاظت ان کے شاہکار کی یاد اور ان کی شہرت وابستہ ہوتی تھی۔
اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان اور عرب کی تعریف و تاریخ پر مختصر نوٹ پیش کیا جائے۔
لغت عربیہ : دنیا کی زبانوں کی جڑ تین بسیط زبانیں ہیں، آرین، سامی،منگولی، عربی سامی زبان کی ایک مقبول اور وسیع فصیح ترین شاخ ہے۔ جس نے ایشیا کے مغڑبی حصہ جزیرہ نمائے عرب میں پرورش پائی او راسلام کے بعد مذہبی سردار ہونے کی وجہ سے اسلام کے اشاعت اور توسیع کےساتھ ساتھ تمام عالم میں پھیل گئی۔
عربی کی شاخوں میں جنوبی شاخ بہت زبردست ہے۔ اس کامرکس یمن تھا۔ شمالی شاخ بھی مختلف قبائل کی طرف منسوب تھی۔ ان سب شاخوں میں قریش کی زبان فصیح ہے جن کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا، او ریہی زبان خلافت راشدہ اور زمانہ مابعد میں علمی اور زندہ زبان قرار دی گئی اور علوم فنون کا سرمایہ اس زبان میں منتقل ہوگیا۔ اقوام عالم کی تاریخ بھی اسی زبان میں محفوظ کی گئی اور ہنوز عرب ،عراق،شام،مصر، الجزائر،مراکش اور زنجبار کے لوگوں کی زبان ہے اور اس وقت مجلس اقوام کی مسلمہ زبان بھی ہوچکی ہے۔
امتہ عربیہ : قدماء او رمتاخرین (محدثین) کے دو بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ قدماء وہ لوگ ہیں جو جزیرہ نمائے عرب کے اصلی باشندے ہیں، ان کے تین طبقے ہیں۔
(الف) عرب بائدہ۔ اس طبقہ کے تاریخی حالات ہم تک نہیں پہنچے۔ سوائے ان حالات کے جو قرآن مجید و احادیث سے معلوم ہوئے او ریہ جدیس،عاد،ثمود،ذعمالقہ،عبدضخم کے قبائل پر مشتمل ہے۔
(ب) عرب عاربہ ۔ یہ قحطان کی وہ اولاد ہیں جوفرات کے کناروں کو چھوڑ کر یمن میں جابسے کہلان اور حمیر اس طبقہ کے دو مشہو رقبیلے ہیں۔
(ج) عرب مستعربہ ۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جنہوں نے بعد میں ''عدنان کے نام سے شہرت پائی اس طبقہ کے مشہور قبائل ربیعہ، مضر، ایاد و انمار ہیں۔
دوسرا حصہ ،محدثین یا متاخرین کا ہے جو اسلام کے بعد بحر اخضر اطلانٹک وشن سے ماوراء بحر فارس تک اور دجلہ فرات کے بالائی حصوں سے لے کر ماوراء جاوا وسوما طرہ تک پھیلے ہوئے ہیں او رمختلف لہجے رکھتے ہیں۔
عربی شاعری کے ادوار : عربی شاعری زمانہ کے لحاظ سے پانچ دور میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔
1۔ دور جاہلیت ۔ جس کی مدت ڈیڑھ سو سال رہی اور جو اسلام کےشروع پر ختم ہوا۔
2۔ دور اوائل اسلام۔ یہ ظہور اسلام سے شروع ہوکر خلافت عباسیہ کے آغاز تک رہا جس میں خلافت امویہ کا زمانہ شامل رہے گا یعنی 132 ھ تک
3۔ دور عباسی۔ خلافت عباسیہ کے قیام سے شروع ہوکر تاتاریوں کے ہاتھ پر ان کے زوال تک قائم رہا 656ھ تک اس دور میں مصر کی فاطمی خلافت کا زمانہ اور اندلس کی امویہ حکومت کا دور شامل ہے۔
4۔ سلطنت ترکیہ۔ سقوط بغداد سے لے کر نئی روشنی کے دور کےشروع تک یعنی 1220ھ تک۔
5۔ دور مششع یا نئی روشنی ۔ یہ مصر میں محمد علی کے خاندان کے حکومت کے آغاز سے 1357ھ کے آخر تک۔
دور جاہلیت (ڈیڑھ سو سال تک ظہور اسلام)
عربی شاعری کی ابتداء ''رجز'' سے ہوئی جو دو چار شعر سے زائد نہ ہوتی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص نے قصیدہ کہا وہ مہلہل بن ربیعہ ہے۔ یہ قصائد ان کے مقتول بھائی کی مرثیہ خوانی او راس کے قصاص کے لیے تحریص و ترغیب پر مشتمل تھے۔ مہلہل پہلا شخص ہے جس نے تیس شعر کا قصیدہ کہا۔ مہلہل کا اصلی نام ''عدی'' تھا، چونکہ اس نے قصیدے کہے اس وجہ سے اس کا نام مہلہل ہوگیا۔ ''ہلہل الثوب'' کی معنی کپڑے بننے کے ہیں۔
مہلہل کے بعد امرؤ القیس، علقمہ،عبید پیداہوئے۔ اس سے پہلے شاعری رجزیہ اشعار یامقطعات تک محدود تھی جن کے لیے عنبر بن عمر بن تیم درید بن زید بن نہدا عصر بن سعد بن قیس، عیلان،زہیربن خباب الکلبی،افوہ اودی اور ابی دواوالا یادی کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ ان کا زمانہ مہلہل سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔
اس میں شک نہیں کہ ان شاعروں سے پہلے بھی ایسے افراد ہوچکے ہوں گے جنہوں نے سبحع سے رجز اوررجز سےمقطعات اور مقطعات سے قصائد نظم کرنے کی ترقی کی ہو، امراؤالقیس خود کہتا ہے۔
عوجا على الطلل المحيل لعلنا ... نبكي الديار كما بكى ابن خذام
تباہ شدہ کھنڈرات کے نشانوں پررونے کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی ابن خذام کی طرح دو آنسو بہا لیں۔
ما أرانا نقول الأ معارا ........ أو معادا من لفظنا مکرودا
ہم جو کہتے ہیں وہ صرف کہے ہوئے الفاظ کی تکرار یا اعادہ سے زیادہ نہیں۔ عنترہ کہتا ہے کہ:
ھل غادر الشعر من مستردم ........ أم ھل عرفت الدار بعد توھم
شعراء نے کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے یا کچھ غورو خوض کے بعد گھر کے نشانات سمجھ میں آگئے۔
شاعر ی کا استعمال: اس دور کی شاعری حسب ذیل عنوانوں میں تقسیم ہوسکتی ہے۔
تشبیب یا غزل : جس میں جنس لطیف کے محاسن کیفیات اور ان کے سفر اور قیام گاہوں کا ذکر ہوتا ہے ،چونکہ عرب اس دور میں ایک خانہ بدوش آزاد قوم رہی اور ان کے قبائل کی قیام گاہوں کا دارومدار پانی کی موجودگی پر تھا۔ ان کا تمام تر سرمایہ اونٹ تھا اور ان کے بہادرانہ شاہکاروں کے لیے شہسواری نہایت اہم تھی، پہاڑوں اور چٹیل میدان اور وہاں کے مختلف پہاڑی درختوں او رپھولوں کے مناظر ان کا ماحول تھا۔ اس لیے اس دور کی غزل میں انہیں اشیاء کاذکر ملے گا۔
مفاخرہ : اس میں خاندانی کارناموں کا جو اکثر خود داری، شجاعت، سخاوت ،مہمان نوازی ،ایفاء ،وعدہ کے بینظیر شاہکار ہوتے تھے،ذکر کیا جاتا تھا۔
مدح : یہ صنف اس دور کے آخری زمانہ کی پیداوار ہے، اور نہ مدح اور خوشامد جاہلیت کے عربوں کے اوصاف اور اصول کے بالکل خلاف ہے۔ شروع میں ممکن ہے کہ کسی محسن کے احسانات کے معاوضہ میں بطور شکر یہ کچھ اشعار کہہ دیئے گئے ہوں۔ اس فن کے علمبردار زہیر، نابغہ اور اعشیٰ ہوئے۔ مدح میں ممدوح کے ذاتی و خاندانی خصائص۔ رجاحت عقل ،عفت ،شجاعت اور اخلاق کو بیان کیا جاتا تھا۔
مرثیہ : کسی مرنے والی کی خوبیوں کوبیان کیا جاتا ہے۔ ایسے مرثیوں میں بڑے بڑے بادشاہوں ،مملکتوں اور قبائل کے نام و نشان مٹ جانے۔جانوروں، شیروں کے مرجانے او رطویل العمر حیوانات سانپ، گدھ وغیرہ کے بالآخر ہلاک ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
ہجا : اس میں کسی آدمی کے ذاتی و خاندانی نقائص کو گنایا جاتا ہے، لیکن اس دور میں زیادہ فحش ..؟؟؟؟؟ گذاف کی حد تک یہ فن نہ پہنچا تھا۔
اعتذار : شاعر اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کی صفائی پیش کرتے ہوئے اپنے خفا ہونے والے ممدوح کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔
وصف نیچری شاعری : یعنی کائنات کے کسی چیز کی تشریح او رکسی منظر کو دلچسپ پیرایہ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے یا تو اس چیز کو بہت مرغوب بنا کر پیش کیا جائے یا اس کو بھیانک صورت اور مکروہ منظر میں بیان کیا جائے۔اس دور میں اونٹ، گھوڑے، درندے،شکار،حشرات الارض، نباتات، آسمان،تارے،بارش،بجلی،پہاڑ،چٹیل میدان،گرمائی اور ربیعی قیام گاہیں اور ان کے بقیہ نشانات گرجا،راہب کے مینار وغیرہ اس فن کے موضوع رہے۔ اسی طرح انسان کے بعض کیریکٹر بھی بیان کیے گئے ہیں۔
حکیمانہ : اس دور میں ایسا کلام کھانے میں نمک کی طرح بہت کم ملتا ہے ۔ لیکن جو ملتا ہے وہ نہایت سادہ،مختصر مقبول اور مؤثر سچائی کے قالبوں میں ڈھلا ہوا۔
خیالات
1۔ اس دور کی شاعری میں معانی صاف اور اکثر حقیقت واقع کےمطابق ملتی ہیں۔
2۔ مبالغہ او رغلو سے احتراز کیا گیاہے۔
3۔ دقیق و غریب مفہوم بہت کم نہ تو تشبیہوں میں جدت نہ استعارے ،کنایات حسن تعلیل وغیرہ ک بھی پتہ نہیں ملتا۔
الفاظ و اسالیب
1۔ الفاظ پوری طرح سے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔
2۔ الفاظ میں شان و شوکت پائی جاتی ہے۔
3۔ چند ایسے قدیم عربی الفاظ ملتے ہیں جو بعد میں متروک ہوگئے۔
4۔ مجاز، معتدل طور پر استعمال کیا گیاہے۔
5۔ اجنبی زبانوں کے الفاظ شاذو نادر ملتے ہیں۔
6۔ صنائع و بدائع یعنی جناس،مقابلہ مطابقت وغیرہ نہیں پائے جاتے۔
7۔ پیرایہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ ایجاز کوترجیح دی جاتی ہے۔
اس دور کے شعرا کے مشاھیر
طبقہ اوّل : امرؤ القیس ،زہیر،نابغہ۔
طبقہ ثانیہ : اعشی،لبید طرفہ۔
طبقہ ثالثہ: عنترہ،عمر بن کلثوم،حارث بن حلزہ،عروہ بن درد،درید بن صمد،ذ مرقش اکبر۔
دوسرا دور اسلامی ( از ظہور اسلام تا 132 ھ)
بوجہ نزول قرآن مجید و ثقافت اسلامیہ کے اس دور کی شاعری میں انقلاب ہوا۔
شاعری کا استعمال
1۔مذہبی عقائد کی ترویج،2۔جنگ او ربہادرانہ مقابلوں کے لیے تحریص و ترغیب،3۔ہجاء،۔وقائع نگاری،5۔ مدح ،6۔ پاکبازانہ تعشق و تغزل۔
خیالات
بلحاظ خیالات کے اس دور کے شعرا زیادہ تر جاہلی شعراہی کے نقش قدم پر چلتے رہے،البتہ جدید اسلامی تہذیب کارنگ اور اس کا اثر کچھ نمایاں رہا۔
الفاظ و اسالیب
الفاظ و اسالیب میں بھی اس دور کی شاعری کا رنگ جاہلیت کے شعراء کا رنگ رہا۔ سنجیدگی اور جاذبیت میں کچھ ترقی ہوئی۔
شعرا کے مشاہیر: کعب بن زہیر۔ خنساء ۔ حطیئہ ۔حسان بن ثابت ۔ نابغہ جعدی۔عمر بن معدیکرب۔ عمرو بن ابی ربیعہ۔ اخطل۔ فرزوق۔ جریر۔ کمیت۔ جمیل۔ کثیر۔ نصیب۔ راعی۔ ذوالرمہ۔
تیسرا دور عباسی (از 133ھ تا 656ھ تک)
اگر یہ کہا جائے توبے جا نہ ہوگا کہ یہی دور اسلامی ترقیوں،فتوحات اور اسلامی تہذیب و حضارت کا ممتاز زمانہ رہا ہے۔ عربی زبان میں تمام علوم و فنون منتقل ہوئے۔تاریخ عالم منضبط کی گئی۔ مختلف تمدنوں سے عرب کو سابقہ پڑا۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے عربی زبان دنیا کی کثیر آبادیوں تک پہنچی اور عربی شاعری عالم کے مختلف تاریخی و جغرافیائی ،تمندی خلط ملط سے بیحد متاثر ہوئی۔
شاعری کا استعمال حسب ذیل اغراض کے تحت رہا
1۔ خاندانی کارناموں پرمفاخرت مذہبی سیاسی علمی کاموں میں تقابل، سیاسی اغراض کے تحت شاعری کا پرچار۔ خاص طور پر بنی اُمیہ کے خلفاء نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔
2۔ خوشامدی اسالیب کا اختیار۔ 3۔ رندانہ شاعری جس میں شراب کی تعریف۔بزم نشاط ۔ ساقی مطرب اور شاہد پرستی، گانے کی توصیف وغیرہ شامل ہے۔ 4۔ وصف نیچرل شاعری،چنانچہ باغات،چمنوں کے مناظر،فطرت کی صناعیوں کی تشریح،شکار اور دیگر تشبیہات وغیرہ۔ 5۔ وعظ،حکمت و فلسفیانہ اقوال ۔6۔ بعض علوم و فنون کے قواعد کو بغرض آسانی حفظ نظم کرنا۔
خیالات: 1۔ مفکرانہ توجیہ۔ 2۔ فرضی خیالات کا تصور۔ 3۔ تشبیہات میں جدت ،استعارے، حسن تعلیل کے لیے نئے نئے پیرائے۔ 4۔ فلسفیانہ نکات او رمذہبی اصول ثابت کرنےکے لیے بہترین دلچسپ طرز۔
الفاظ و اسالیب: 1۔ الفاظ غریبہ کا ترک استعمال۔2۔ عجمی الفاظ کی زیادتی۔3۔ پیرایہ کی لطافت لیکن الفاظ کی شوکت کے بقا کے ساتھ۔ 4۔ صنائع بدائع میں جدید اختراعات او ران کی کثرت۔
مشہور شعرا: بشار،بونواس،مسلم،ابوالعتاہیہ،ابن الرومی، ابوتمام بختری،ابن المعتز ،ابن ہانی،امیر تمیم،ابوفراس،ابوالعلاء المعری شریف رضی
چوتھا دور ترکی حکومت کا (از 657ھ تا 1220ھ)
اس دور میں چونکہ اکثر اسلامیہ ممالک کے زمام سلطنت عجمی بادشاہوں کے ہاتھ آچکی تھی۔ اس لیے عربی شعراء کی سرپرستی میں بہت کمی ہوگئی۔ نیز اس زمانہ سے شعر گوئی کو کسب مال و جاہ کاذریعہ بنانا موقوف ہوگیا۔نیز صوفیانہ رنگ چھا گیا۔
شاعری کااستعمال : 1۔ نعتیہ قصائد دربار رسالت سے۔ التجاء ۔مناجات بہ بارگاہ رب العزّت۔2۔ اولیائے کرام کی مدح۔ 3۔ صوفیانہ شاعری۔ 3۔ غیر حقیقی غزل او ربجائے محبوبہ کے محبوب کاذکر، جو ایرانی شاعری کا پرتو تھا اور صوفیانہ مذاق کی وجہ سے اکثر علماء و مشائخ نے اس طرز کو رائج کیا تھا۔ 5۔بدائع صنائع کی خاطر غزلیات و مقطعات کا کہنا۔6۔ نیچرل شاعری رہٹ، تکیہ،فرش، جانماز،پنکھا،چھری، دوات،چراغ، بخودانی وغیرہ چیزوں پر طبع آزماوی۔7۔ رندانہ شاعری۔ 8۔ فحش ہجو۔9۔ پہیلیاں (معمے)۔
خیالات: نازک خیال۔ ضرب المثل او رفلسفیانہ نکات میں جدت پیدا کرنے کی بجائے صرف تشبیہ اور استعارات کے استعمال پر زوردیا گیا۔
الفاظ و اسالیب : 1۔صرف آسان الفاظ کا استعمال۔چنانچہ پرشوکت لفظ کا استعمال بھی ترک ہوا، بلکہ عامی اور ترکی الفاظ بھی استعمال ہونے لگے۔ 2۔ آسان ترکیب اور عامی مثلوں کا استعمال۔ 3۔ صنائع بداوع پر زور دیاگیا خصوصاً فن توریہ اور جناس پر۔4۔ تصغیربے نقطہ، یا صرف نقطہ دار الفاظ کا استعمال لزوم مالایلزم مالا یستحیل بالا نعکاس کی صنعتیں۔ تاریخی مادے۔ 5۔ مشہور اشعار کی تضمین، تشطیر، تخمیس۔6۔ اقتباس۔
مشہور شعراء : شیخ شرف الدین انصاری(متوفی 662ھ)۔ ابن جمال الدین شہاب الدین تلعفری (المتوفی675ھ)۔ ابن الوردی (المتوفی 687ھ)۔ امام بوصیری۔ابن حجۃ (المتوفی 837ھ) ۔صفی الدین حلّی فخر الدین بن مکانس (المتوفی 864ھ) ابن معتوق۔
پانچواں دور نئی روشنی (1221ھ سے 1357ھ تک )
اس دور میں مغربی تہذیب کااثر اور مادہ پرستی کی طرف میلان سیاسی ہیجان جدید فلسفی و طبعی نظریے او راختراعات و ایجادات نیز مختلف اقوام کا گہرا ربط و ضبط یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے شاعری بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔
عربی ممالک خاص طور پر شام اور مصر میں امیر مبلغین کی مساعی۔ یورپ کے مستشرقین کی کوششیں یہ سب امور ایسے پیدا ہوچکے ہیں جس سے عربی شاعری میں ایک جدید انقلاب نمایاں ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اس دور کے نصف اوّل تک تو سخت جمود رہا اور شاعری میں کوئی ترقی نہ ہوسکی لیکن موجودہ دور میں عربی ممالک کی پھر لغت فصحیٰ کی طرف توجہ شروع ہوئی اور نئے نئے شاعر پیدا ہوئے۔
استعمال : 1۔ فطرتی مناطر،وجدانات،جذبات پرطبع آزمائی ہونے لگی۔2۔ جدید آلات ریل، بجلی، ٹیلی فون وغیرہ پر اشعار کہے گئے۔
اسالیب : موجودہ دور کے کلام میں بدیع جناس کی کمی کی گئی اور سادگی کی طرف رجوع کیا گیا چنانچہ اس صدی کے اکثر شعراء نے چوتھی پانچویں صدی کے شعراء کارنگ اختیار کرلیا ہے۔
شعراء:محمود سامی بارودی۔ حضنی ناصف بک۔ شوقی شیخ شہاب۔
میں نے بوجہ طوالت جغرافیائی لحاظ سے عربی شاعری پر تبصرہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس لحاظ سے بھی عربی شاعری پر کافی کچھ لکھا اور کہا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر یمن،حجاز،شام،مصر،ہند،عراق، اندلس وغیرہ کے شعراء کے درمیان اپنے ممالک کے رسم و رواج اور عقائد کے لحاظ سے بہت کچھ فرق پایا جاسکتا ہے۔نیز رعایا اور بادشاہوں اور شاہی افراد کی شاعری میں بھی بہت کچھ فرق ہوسکتا تھا۔ اب ہم عربی شاعری کو پانچ عنوانوں میں تقسیم کردیتے ہیں او رہر عنوان کے تحت ان ضروری خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن سے عربی شاعری کا درجہ اور امتیاز معلوم ہوسکے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔جو یہ ہیں غزل،فخر،مدح،وصف،حکیمانہ۔
غزل: عربی شاعری میں سب سے زیادہ غزلیات پائی جاتی ہیں چنانچہ مطلق غزلیات کو نظر انداز بھی کردیں تو مدحیہ قصائد بھی اکثر غزل ہی سے شروع ہوتےہیں۔
1۔ عربی زبان میں غزل مسلسل ہوتی ہے۔جس میں محبوب کا سراپا یا وصل و ہجر کا واقعہ یا کوئی دلچسپ واردات مفصل طور پربیان کی جاتی ہے۔
ابی ابن ربیعہ:
ليت هنداً أنجزتنا ما تَعدْ ........وشَفَتْ أنفسنا مما تَجِدْ
واستبدتْ مرة ً واحدة ً ........ إنما العاجز من لا يستبدْ
ولقد قالت بحارات لھا ........ ذات یوم و تعرت تبترد
أکما ینعتني تبصرنني ........ عمر کن اللہ أمر لا یقتصد
فَتَضاحَكنَ وَقَد قُلنَ لَها........حَسَنٌ في كُلِّ عَينٍ مَن تَوَد
حَسَدٌ حُمِّلنَهُ مِن أَجلِها ........وَقَديماً كانَ في الناسِ الحَسَد
'' کاش کہ ہند اپنا وعدہ پورا کرتی اور ہماری روحانی تکلیفوں کا علاج کردیتی یک مرتبہ خود نماوی و خودداری ظاہر کرنے لگی، بے شک خود داری نہ کرنا تو عاجزی کا کام ہے۔ ایک روز اپنے کپڑے اتارے ہوئے تھی او رہوا کھا رہی تھی اپنی سہیلیوں (پڑوسنوں) سےکہنے لگی،تمہاری جان کی قسم کیا میں واقعی ایسی ہی حسین ہوں،جیساکہ میرا عاشق تعریف کرتا ہے یا وہ کچھ مبالغہ کرتا ہے، سب ہنس کر کہنے لگیں کہ ''چاہنے والے کی آنکھ میں اپنے محبوب کی ہر چیز قابل تعریف ہی ہوتی ہے۔'' اور یہ صرف حسد سے کہا اور قدیم زمانے سے حسد تو چلاآتا ہے۔''
امیر تمیم :
عانقْت لامَ صُدْغها صادُ لثمي ........فأرتها المرآةُ في الخد لِصّا
فاسترابت بما رأت ثم قالت.......أكتابا أرى ولم اَرَ شخصا
ودَعَتْني لمحوِه فتمكَّن ........ من الوجنتين لَمْساً وقرصا
ثم قالت ألا امْحُهُ محو من يج ........هد في محوِه ومن يتقصّى
قلت بالقشط يمَّحِي قالت اقشط ........بالثنايا وأتْبع القشط مَصّا
قلت إن الذي أمرتِ به فر ........ ضٌ علينا مؤكّد ليس يُعصى
ورأت إثر ما محوت فقالت .......كان لصّا فصار والله فَصّا
قلت إن الفصوص تطبع باللّث ........ م على خدِّ كلُِّ من كان رَخْصا
(ترجمہ) ''اس کے زلف کے لام سے میرے چومنے کا صاد ہم آغوش ہوا یعنی میں نے اس کا بوسہ لیا۔ آئینہ میں دیکھنے سے اس کے رخسار پر نشانہ نظر آیا، وہ اس سے جھینپی اور مشکوک نگاہ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ کچھ کتابت کا نشان نظر آرہا ہے لیکن لکھنے والے کا تو پتہ نہیں مجھے بلایااس نشان کے میٹنے کی فرمائش کی۔ میں نے دونوں رخساروں کو اچھی طرح چوما اور کاٹا۔ کہنے لگی اس کو ایسا مٹا دو کہ جس کے مٹانے میں پوری کوشش صرف کرنے کا پتہ چلے۔میں نے کہا کہ اس کو تو چھیل کر مٹایا جاسکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں دانتوں سے چھیل دو اور پھر چوس لو، میں نے کہا کہ یہ ایسا فرمان ہے جس کی تعمیل فرض ہے او راس میں فروگذاشت جائز نہیں۔میرے مٹانے کے بعد اس نے اس کے نشان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ نشان تھا اب تو نگینہ بن گیا، میں نے کہا بے شک ایسے نگینے ہی بذریعہ بوسے نرم رخسار پربنائے جاتے ہیں۔''
ایضاً :
شبهتها بالبدر فاستضحكت و قابلت قولي بالنكر
و سفهت قولي وقالت:متى سمجت حتى صرت كالبدر؟
البدر لايرنو بعين كما أرنو،ولايبسم عن ثغر
ولا يميط المرط عن ناهد ولا يشد العقد في نحر
من قاس بالبدر صفاتي،فلا زال أسيرا في يدي هجري!
(ترجمہ) ''میں نے مجبوبہ کو چاند سے تشبیہ دی ، اس نے ہنس کر میرے قول کی تردید شروع کی، اس نے میرے کلام کا مذاق اڑایا او رکہنے لگی،اتنی میں کب بدمذاق ہوگئی کہ چاند جیسی بن گئی،نہ تو چاند میری طرح آنکھ سے ناز و انداز کی نظر ڈال سکتا ہے او رنہ میری طرح دانت دکھا کر مسکرا سکتا ہے او رنہ ابھرے ہوئے سینہ سے چادر ہٹاتا ہے او رنہ سینہ کو مالا سے مزین کرتا ہے جو میرے اوصاف کاچاند سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ فراق کے ہاتھوں پابہ زنجیر رہا کہ اس نے میری اس قدر تحقیر کی۔''
البھا زہیر المتوفی 656ھ
يعاهدني لاخانني ثم ينكث === وأحلف لا كلمته ثم أحنث
وذلك دأبي لايزل ودأبه === فيا معشر العشاق عنا تحدثوا
أقول له صلني يقول نعم غدا === ويكسر جفنا هاذئاّ بي ويعبث
وما ضر بعض الناس لو كان زارني === وكنا خلونا ساعة نتحدث
أمولاي إني في هواك معذب === وحتام أبقى في الغرام وأمكث
فخذ مرة روحي ترحني ولا أرى=== أموت مرارا في النهار وأبعث
فاني لهذا الضيم منك لحامل === ومنتظر لطفا من الله يحدث
أعيذك من هذا الجفاء الذي بدا=== خرئقك الحسنى أرق وأدمث
ترددن الناس في فأكثروا === أحاديث فيها مايطيب وينخبث
وقد كرمت في الحب مني شمائل === ويسأل عني من أراد ويبحث
(ترجمہ) '' وہ مجھ سے معاہدہ کرتا ہے کہ مجھ سے بیوفائی نہ کرے گا پھر عہد شکنی کرتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے کبھی نہ بولوں گا۔ پھر قسم توڑ دیتا ہوں ۔ یہ میری اور اس کی مسلسل عادت ہے۔اے لوگو! سنو اور سناؤ۔ میں اس سے وصل کی درخواست کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ کل، اور آنکھ مار کے میرا مذاق اڑاتا ہے ۔ وہ اگر مجھ سے ملے یا تنہائی کا موقع دے تو کسی کاجی کیوں جلتا ہے۔میری سرکار میں آپ کے عشق میں معذب ہوں، کب تک اس عذاب میں رہوں ایک ہی مرتبہ مجھے مار ڈالو، تاکہ آرام کی نیند سو جاؤں۔یہ کیا مصیبت ہے کہ دن میں کئی بار مرتا ہوں او رپھر زندہ کیا جاتا ہوں میں نے آپ کے یہ ظلم سہے او راب خدائے تعالیٰ سے مہربانی کا منتظر ہوں۔آپ جیسے خوش اخلاق ہستی سے ایسی جفاکیوں ہورہی ہے، لوگ میرے بارے میں مختلف اچھی باتیں کہتے ہیں لیکن آپ کی محبت میں میرے خصائل منزہ ہیں جس کو چاہے اس کی تحقیقات کرے۔''
2۔ عرب کا معشوق عفت و عصمت کا حرم نشین ہوتا ہے وہاں تک رسائی مشکل ہوتی ہے اگر وہاں رخ کریں تو تلواروں کا سامنا ہوتا ہے۔چنانچہ متنبّی کہتا ہے:
ديار اللواتي دارهن عزيزة ، بطول القنا يحفظن لا بالتمائم
''میں ان حرم نشینوں کے گھر کا ذکر کرتا ہوں جن کی رہائش گاہیں گندم گوں نیزوں کے ذریعے محفوظ ہوتی ہیں نہ کہ تعویذوں سے۔''
عرب میں محبوبہ کے ایسے محافظوں کو رقیب کہتے ہیں، الغرض عرب کے عاشقانہ جذبات مناسب پرجوش شریفانہ اور سچے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایرانیوں کا محبوب شاہد بازاری ہوتا ہے۔جو ہر ایک کے ہاتھ لگ سکتا ہے اس کے چاروں طرف عشاق کا جمگھٹا لگا رہتا ہے۔
3۔ عربی غزلیات میں خود داری او رعزت نفس کے جذبات قائم رہتے ہیں۔ عرب کا عاشق طالب ہے، گدا نہیں،جانباز ہے،غلام نہیں، آمادہ مصائب ہے لیکن ذلیل نہیں۔ وہ معشوق سے مخاطب ہوکر کہتا ہے۔
فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم ... لشيءٍ ولا أني من الموت أفرق
(ترجمہ) '' یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارے بعد میں ذلیل ہوگیا او رنہ یہ کہ پاؤں کو زنجیر میں بند پاکر اپنے وقار کے خلاف حرکت کرتا ہوں۔''
لیکن ایران کا شاعر اپنے آپ کو ذلیل قرار دیتا ہے۔ عاشق کی گلی کا کتا کہتا ہے۔
4۔ فارسی شاعری میں معشوق حسن ِصور ت کے لحاظ سے جس قدر بےمثل و بےنظیر ہے اسی قدر اخلاق کے لحاظ سے دنیا کے تمام عیوب کا مجموعہ ہے۔ وہ جھوٹا ہے، بدعہد ہے۔ ظالم ہے،سفاک ہے،مکار ہے،دغا باز ہے، فتنہ گر ہے،حیلہ ساز ہے،شریر ہے،کینہ پرور ہے،نہایت احمق ہے،ہرایک کی بات مان لیتا ہے اور ہرایک کے قابو میں آجاتا ہے۔
فخریہ : شعرائے عرب صاحب تیغ و علم ہوتے ہیں،اس لیے انہوں نے اپنے معرکے لکھے اور فخریہ قصائد نظم کیے، عمر بن ہند نے یہ معلوم کیا کہ عرب میں عمرو بن کلثوم کے سواکوئی ایسا شخص نہیں جس کی ماں عمرو بن ہند کی ماں کی اطاعت و خدمت سے انحراف کرے۔ عمرو بن ہند اور اس کی ماں نےقبیلہ کے ممتاز افراد کو دعوت دی۔ زنانہ دعوت خانہ میں عمرو بن ہند کی ماں نے عمر بن کلثوم کی ماں سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرکے اس کے اٹھا لانے کو کہا۔ عمر بن کلثوم کی ماں واتغلبا، ہائے تغلب کہہ کر چیخی، عمر بن کلثوم اور اس کے ساتھیوں نے تلوار نیام سے کھینچ لی۔ عمرو بن ہند کا سرقلم کرلیا اور ایک مشہور قصیدہ کہا جو کعبہ میں آوازیں کیا گیا اور اس کو معلقات کی فہرست میں درج ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ اس قصیدہ سے قبیلہ ثعلب میں شجاعت ،بہادری ،دلیری بڑھ گئی جو کئی سو سال تک قائم رہی، یہ قصیدہ اس قبیلہ کے بچہ بچہ کو یاد تھا۔
أَلاَ هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِيْنَـا... وَلاَ تُبْقِي خُمُـوْرَ الأَنْدَرِيْنَ
أَبَا هِنْـدٍ فَلاَ تَعْجَـلْ عَلَيْنَ... وَأَنْظِـرْنَا نُخَبِّـرْكَ اليَقِيْنَ
بِأَنَّا نُـوْرِدُ الـرَّايَاتِ بِيْضـاً... وَنُصْـدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِيْنَـا
بِاَيِّ مَشِيْئَـةٍ عَمْـرُو بْنَ هِنْـدٍ... نَكُـوْنُ لِقَيْلِكُـمْ فِيْهَا قَطِيْنَـا
بِأَيِّ مَشِيْئَـةٍ عَمْـرَو بْنَ هِنْـدٍ... تُطِيْـعُ بِنَا الوُشَـاةَ وَتَزْدَرِيْنَـا
أَلاَ لاَ يَجْهَلَـنَّ أَحَـدٌ عَلَيْنَـا... فَنَجْهَـلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِيْنَـا
إِذَا بَلَـغَ الفِطَـامَ لَنَا صَبِـيٌّ ... تَخِـرُّ لَهُ الجَبَـابِرُ سَاجِديْنَـا
(ترجمہ) '' اپنا ساخر نکالو اور صبوحی شراب کا دور چلنے دو، اندرین کی شراب سب ختم کرڈالو۔ اے پدر ہند جلد بازی سے کام نہ لو۔ ہم کو مہلت دو۔ ہم تم کو حقیقت سمجھا دیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے سفید نشانوں کو لے کر جنگ پرجاتے ہیں اور سرخ اور خون سے سیراب ہوکر پلٹتے ہیں۔ عمر بن ہند تو نے کس خیال سے چغلخوروں کا کہنا مان کر ہم کو حقیر سمجھا۔ خبردار کوئی بھی ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ نہ کرے ورنہ ہم ان کی جہالت کا جہالت سے جواب دینے کو تیار ہیں۔
جب ہمار ابچہ شیر خواری کا زمانہ ختم کرتا ہے تو اس کے سامنے بڑی بڑی زبردست ہستیوں کو سرنگوں ہونا پڑتا ہے۔ علامہ شبلی کہتے ہیں کہ عور کرو شعراء فارس اس کے مقابلہ میں کس چیز پر فخر کرسکتے ہیں، نظامی،عرفی نے بڑے زور کے فخریئے لکھے ہیں لیکن فخر کی ساری کائنات یہ ہے کہ ہم اقلیم سخن کے بادشاہ ہیں۔ الفاظ او رحروف ہمارے باجگزار ہیں۔ مضامین ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے تو یہ کہہ دیا کہ ہم پری پیکر ہیں۔ چنانچہ عرفی کہتا ہے ؎
سربرزدہ ام بامہ کنعان زیکے جیب ........ معشوق تماشا طلب و آئینہ گیرم
میگوئم و اندیشہ ندارم زطریفاں ........من زہرہ رامش گروہن بدر منیرم
ایرانی شاعر ہمیشہ غلام رہے۔غلامی میں پلے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے پیدا ہوئے۔
شعر4۔83 صفی الدین حلی، المتوفی 570ھ
سل الرماح العوالي عن معالينا
واستشهد البيض هل خاب الرجا فينـا
لقد مضينا فلم تضعف عزائمنا
عمــــا نــروم ولا خابت مساعيـنـــــا
قوم اذا خاصموا كانوا فراعنة
يوما وان حكــمـــوا كانوا موازينــــا
إذا ادّعوا جاء ت الدنیا مصدقة ........ دان دعوا لأیام اٰمینا
انا لقوم أبت أخلاقنا شرفا
أن نبتـــدي بالأذى من ليس يؤذينــــا
قوم اذا خاصموا كانوا فراعنة
يوما وان حكــمـــوا كانوا موازينــــا
(ترجمہ) ''بلند نیزوں اور سفید تلواروں سے ہمارے بلندکارناموں کے متعلق دریافت کرو، کہ کیا کبھی ہم سے جو توقعات تھیں اس میں ناکامی ہوئی۔ ہم نے کوشش کی او رہمارے پختہ ارادے مقصد کے حصول میں کبھی کمزور نہ ہوئے اور نہ ہماری کوششیں ناکام رہیں۔ ہم ایسی قوم ہیں کہ اگر ہم کو فریق بناگیا تو ہم فرعون بنے اور کسی کا جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر خود ہم پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا تو ہم عدل کی ترازو ثابت ہوئے۔ اگرہم نے کوئی دعویٰ پیش کیا تو دنیا نے اس کی تصدیق کیاور اگرہم نے دعا کی تو زمانہ کو آمین کہنا پڑا۔ الغرض جو دعویٰ کیا ثابت کرکے چھوڑا او رجو اُمید کی گئی پوری کی گئی۔ ہمارے شریفانہ اخلاق سے یہ بہت ہی بعید ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تکلیف دیں یا ان کو چھیڑیں جو ہم کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے کارنامے روشن، ہمارے واقعات بہت خطرناک،ہماری رہائش گاہیں سرسبز او رہماری تلواریں خون اعدا س سرخ ہیں۔''
عنترہ عبسی المتوفی ق ھ 7۔
حكم سيوفك في رقاب العذل = وإذا نزلت بدار ذل فارحل
وإذا الجبان نهاك يوم كريهة = خوفا عليك من ازدحام الجفل
فاعص مقالته ولا تحفل بها = واقدم إذا حق اللقافي الأول
واختر لنفسك منزلا تعلو به= أو مت كريما تحت ظل القسطل
وبذابلي ومهندي نلت العلا = لا بالقرابة والعديد الأجزل
لا تسقني ماء الحياة بذلة = بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم = وجهنم بالعز أطيب منزل
(ترجمہ) ''نکتہ چینوں کی باتوں کی پرواہ نہ کر، ان کو تو تلوار سے قتل کردے او رجب کسی ذلت کے مقام پر قیام کیا ہو تو وہاں سے کو چ کردے۔ جب بزدل تجھے جنگ کے روز فوج کشی سے روکے اس خ وف سے کہ تو ہلاک ہوجائے تو اس کے قول کی مخالفت کر او راس کی پروا مت کر او رجب جنگ مقرر ہوجائے تو صف اوّل میں رہ اور آگے بڑھ۔ اپنے آپ کے لیےترقی کی کوشش کر یا جنگ میں جان دے دے، میں نے جو ترقیاں کیں وہ صرف اپنی تلوار او رنیزے کے بل پر کیں نہ کہ کسی رشتہ داری یا بڑی فوج کی مدد سے۔ ذلت کے ساتھ تو میں آب حیات بھی پینے کو تیار نہیں او رعزت کے ساتھ تو اندرائن کا جام بھی پی لوں۔ آب حیات ذلت کے ساتھ دوزخ ہے اور دوزخ میں بھی اگر عزت حاصل ہو تو وہ خوشگوار مقام ہے۔''
مدح : عرب مدحیہ اشعار کہنا عار سمجھتے تھے۔ شروع شروع میں کسی محسن کے احسان کے شکریہ میں چند اشعار کہہ دیئے جاتے تھے۔جیسا کہ امراؤالقیس نے بنی تمیم کی مدح میں کہا ہے جو اس کے محسن معلی کا خاندان ہے کیونکہ معلی نے اس کو منذر بن ماء السماء سے پناہ دی تھی جو امرؤ القیس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جس نے اس کے بھائیوں کودیر مزینا کے واقعہ میں قتل کیا۔
أقرحشا امرؤالقیس بن حجر ........ بنوتیم مصابیح الظلام
اس شعر کی وجہ سے بنیتیم ''مصابیح الظلام'' کے نام سے موسوم ہوئے۔ نابغہ پہلا شخص ہے جس نےمدحیہ کہنا او رانعام حاصل کرنا شروع کیا۔ زہر بن ابی سلمیٰ نے بھی ہرم بن سنان کی مدح کی او رہرم نے اس کو بہت نوازا۔اعشی نے اس کو پیشہ بنا لیا اور عرب کے سرداروں کے علاوہ شاہان عجم کے دربار تک پہنچا او رانعامات و صلے حاص کیے۔ حطیئہ نے اس بارے میں شاعری کو نہایت درجہ گرا دیا لیکن پھر بھی مجموعی لحاظ سے عربی شعراء نے اپنی آن بان قائم رکھی اور مدحیہ اشعار کہنا عرب کے خود داری کے اصول کے خلاف رہا، چنانچہ ایک رئیس نے ایک عرب شاعر سے مدح کہنے کو کہا تو کہہ دیا ۔ ''افعل حتی اقول''۔
عرب شعراء اکثر اس وقت مدح لکھتے تھے جب ممدوح کوئی زبردست معرکہ سرکرتا۔معتصم باللہ نے ایشیائے کوچک میں عموریہ فتح کیا تھا۔ چند روز کے بعد عیسائیوں کا قبضہ ہوگیا اور ایک دن ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کو پکڑا۔ عورت چلائی اور وامعتصما کہا (ہائے معتصم) یہ اطلاع دربار خلافت میں پہنچی۔ معتصم نے پوچھا عموریہ کدھر ہے۔ سمت بتلائی گئی اس سمت رُخ کرکے لبیک لبیک کہا اور فوجوں کو تیاری کا حکم دیا ،دربار کے بعض منجمین نے کہا یہ وقت روانگی کے لیےمناسب نہیں ہے اگر اس وقت فوج روانہ ہوگی تو شکست ہوگی۔معتصم نہ مانا۔ ایک لاکھ سے زائد فوج لےکرنکلا اور عموریہ فتح کیا، عورت کی تلاش ہوئی جب سامنے آئی تو کہا کہ آج میں نے مزے سے کھاناکھایا، جب اس جنگ سے واپس آیا تو دربار میں منجم بھی تھا۔ ابوتمام نے یہ قصیدہ پڑھا۔
السیف أصدق أنباء من الکتب ........ في حدّه الحدبین الجدو اللّعب
والعلم في شھب لأرماح لامعة ........ بین الخمسین لافي السبعة الشھب
''تلوار بہ نسبت کتابوں کے زیادہ سچ بولتی ہے اس کی باڑھ سنجیدگی اور مسخرا پن کی حد فاصل ہے، علم برچھیوں او رنیزوں کے ستاروں کے چمکتے شعلوں میں چمکتا ہے نہ کہ سبعہ سیارہ میں۔''
ہارون الرشید کے زمانہ میں ایشیائے کوچک عیسائیوں کے قبصہ میں تھا اور ان سے بطور خراج رقم وصول ہوتی تھی۔ جب نائس فورس تخت نشین ہواتو اس نے ہارون الرشید کو لکھ دیا کہ میرے پہلے یہاں کی حکمران ایک عورت تھی اس سے طے شدہ معاہدات کا میں ذمہ دار نہیں میں خراج نہ دوں گا۔ ہارون الرشید نے یہ خط پڑھا تو بہت برہم ہوا۔ دربار کےلوگ منتشر ہوگئے۔ہارون الرشید نے فوراً صرف اتنا جواب لکھا۔
اوسگ رومی، اس خط کا جواب سننے سے پہلے تو دیکھ لے گا ۔حملہ کی تیاری کی اور ایشیائے کوچک کے دارالسلطنت کو فتح کرکے واپس آیا۔ نائس نے پھر دوبارہ بغاوت کی ۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ یہ اطلاع ہارون الرشید تک پہنچا سکے۔ بالآخر ایک شاعر نے دربار میں جاکر یہ قصیدہ پڑھا۔
نقض الذي أعطیته یقفور ........ فعليه دائرة البو ارتدور
ہارون الرشید نے ٹھنڈی سانس بھری او رکہا کیا ایسا ہوا ہے۔ شدت کے جاڑے تھے۔ لیکن اسی وقت فوجوں کو حکم دیا، وہاں ہرقل کی تصویرکھنچوائی او راپنے تینوں بیٹوں کے نام لکھوائے۔ایک مہینہ تک محاصرہ کیا اور فتح کرکے واپس ہوا۔ درباری شعراء نے قصائد پڑھے۔
عرب اور ایران کی شاعری میں یہ مابہ الامتیاز چیز ہے کہ عرب کے مدحیہ قصائد وقائع نگاری سے مملو ہوتے ہیں اور اس پیرایہ میں واقعات لکھتے تھے۔غرض جذبات میں تحریک اور ائندہ دلوں میں ایسے معرکے سر کرنے کے ولولے پیدا ہوجاتے تھے۔ جس کی مدح کی جاتی تھی وہ اس کے مستحق ہوتے تھے او رمدح میں جو کہا جاتاتھا سچ ہوتا تھا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں فارسی قصائد میں یہ شرطیں کبھی جمع نہیں ہوتی، اولاً تو اکثر ایسے لوگوں کی مدحیں لکھی گئیں جو سرے سے مدح کے مستحق نہ تھے یا تھے تو ان کے واقعی اوصاف نہیں لکھے گئے بلکہ تمام قوت مبالغہ اور غلو میں صرف کی گئی۔ اکبر خانخاناں شاہجہان کے سینکڑوں معرکے تاریخی یادگار ہیں جن کے بیان سے مردہ دلوں میں جنبش پیداہوسکتی ہے۔ عرفی، نظیری، فیضی و غیرہ نے ان لوگوں کی مدح میں سینکڑوں پُرزور قصائد لکھے لیکن ان معرکوں کاکہیں نام تک نہ آیا۔
الغرض مدحیہ قصائد اقوام اور بہادران قوم کے شاہکار او ران کے کارناموں کے تاریخی اوراق ہوتے ہیں جو ان بہادروں او رکارگزار افراد کے کارناموں کو زندہ رکھتے اور مرنے والوں کو حیات ثانیہ بخشتے ہیں۔
ترقی یافتہ قوموں کے شریفانہ اخلاق کوزندہ رکھنے والی چیز ان کے تاریخی واقعات کا زندہ رہنا ہے او ربہ نسبت خشک تاریخی قصوں کے یہ کام مدحیہ قصائد سے بہت خوبی سے انجام پاتا ہے ، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے علاوہ یہ آنے والی نسل کے لیے باعث تحریک ہوتے ہیں کہ اگرہم بھی دنیا میں کوئی کام کریں گے تو ہمارا نام بھی زندہ رہے گا۔
نیچرل شاعری (وصف) :ارسطو کی تشریح کے مطابق شاعری مصوری ہے۔ بلکہ شاعری کادرجہ مصوری سےبہت بڑھا ہوا ہے ۔ مصور صرف مادی اشیاء کی تصویر پیش کرتا ہے او رممکن ہے کہ مصور اگر نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے تو کسی ایک عصبی تاثر یعنی نفسانی کیفیت رنج، خوشی، استعجاب پریشانی بے تابی وغیرہ بھی تصویر سے ظاہرکرسکے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جہانگیر کے سامنے ایک عورت کی ایسی تصویر پیش کی گئی تھی جس کے تلوے سہلائے جارہے تھے اور گدگدی کا اثر اس کے چہرہ پرطاری تھا۔ تاہم تصور سےگونا گوں واقعات و حالات ظاہر کرنا مشکل ہے۔ خصوصاً غیر مادی امور انقلابات اور خیالات اورواقعات کےسلسلہ کو تصویر سے واضح کرنا ناممکن سا ہے بجز اس کے کہ قلمی صورت میں مجموعہ تصاویر ہے۔ اس کو واضح کیا جائے جو موجودہ زمانہ کا نہایت ترقی یافتہ فن ہے، پھر بھی صرف خاموش تصویر اس کام کو پورا انجام نہ دے سکی اور اس کے لیے شاعری و موسیقی کی ہم آہنگی ضروری معلوم ہوئی اور اب ناطق فلم نے اس فن کو مکمل کیا۔ عربی نیچرل شاعری شروع میں پہاڑوں کی بلندی ، قافلوں کی روانگی، اونٹ ، گھوڑے، سفر، قیام گاہوں کے کھنڈر وغیرہ کے بیان تک محدود رہی لیکن بعد میں چل کر مختلف چیزوں کی تشریح وصف کے لیے اس کا دائرہ وسیع ہوا ہے، یہا|ں تک کہ اس فن سے معموں کےفن نے جنم لیا۔
سری رفاء (ہلال)
وکان الھلال لون لجین ........ غرقت في بحیرة زرقاء
''چاند ایسا معلوم ہوتا ہےکہ وہ چاندی کی مچھلی ہے۔ نیلگوں سمندر میں غوطہ لگا رہی ہے۔''
امراؤ القیس (رات)
ولیل کموج البحر اأرخی سدوله ........ علي بأنواع الھجوم لیبتلي
''رات نے قسم قسم کے ہم و غم کے ساتھ اپنے پردے مجھ پر ڈال دیئے وحشت او ربھیانک پنے میں یہ رات سمندر کی موج کی طرح معلوم ہوتی ہے۔''
(رات)
لیلتي ھذه عروس من الزنج ........ علیھا قلائد العقیان
''میری رات ایک حبشی کی دلہن معلوم ہوتی ہے جس پر موتیوں کے ہاں ہیں۔''
وسھیل کوجنة الحب في اللو ........ ن وقلب المحب في الحفقان
''ستارہ سہیل رنگ کے لحاظ سے رخسار معشوق جیسا سرخ اور جھپکنے میں عاشق کے دھڑکنے والے دل کی طرح معلوم ہوتا ہے۔''
گھوڑوں کی تیز اور نرم رفتار (متنبّی)
يطئ الثرى مترفقا من تيهه فكاس آس يحبس عليلا
''وہ زمین پر اپنے ناز انداز سے اس طرح قدم رکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی حکیم صاحب ہیں جو کسی بیمار کی نبض دیکھ رہے ہیں۔''
ولووطئت في سیرھا جفن فائم ........ بأخفا فھالم ینتبه من منامه
''وہ اپنی رفتار میں اپنے پاؤں اتنے سبک رکھتا ہے کہ اگر سونے والے آدمی کی پلکوں پر رکھے تو اس کی نیند میں خلل بھی نہ ہو۔''
آگ ۔
رأيت یاقوتة مشبکة ........ تطیر عنھا قراضت الذھب
''ایک شعلہ فشاں یاقوت ہے جس سے سونے کی چنگاری اُڑ رہی ہے۔''
عاشق کالاغری کے متعلق۔
امیر تمیم:
لو فتَّشوا جِسْميَ ما أبصروا, غيرَ الأسى يَسْرَح بين الثّياب
''اگر میرے جسم کو تلاش کیا جائے تو معلوم ہوگا ایک مجسم رنج ہے جو کپڑوں میں ملفو ف حرکت کررہا ہے۔''
متنبّی ۔
روح تخلل في مثل الخلال فلو ........ أطارت الریح عنه الثوب لم بین
''میری روح ایک خلال نما جسم کے درمیان ہے اگر ہوا سے کپڑے اُڑ جائیں تو اس کا دکھاؤ دینامشکل ہوگا۔'' (ایضاً)
ولو قلم ألقیت في شق رأسه ........ من السقم ماغیرت في خط کاتب
''بیماری سے اتنا گھل گیا ہوں کہ اگر قلم کی زبان کے شگاف میں رکھ کر کاتب لکھنا چاہے تو خط میں کوئی تغیر واقع نہ ہوگا۔''
پانی میں تاروں اور چاند کے عکس کا منظر ۔معّری:
به غَرْقَى النّجُومِ: فبيْنَ طافٍ=ورَاسٍ، يَسْتَسِرّ ويُسْتَبان
أجَدَّ به غَواني الجِنّ لَعْباً،=فأعْجَلَها الصّبَاحُ، وفيه جان
فَصِيمٌ، نِصْفُهُ في الماء بادٍ،=ونِصْفٌ في السّماء به تُزان
''اس تالاب میں کچھ ستارے غوطے لگا رہےہیں کسی کا سرپانی سے باہر آتا ہے او رکسی کا سراندر جاتا ہے۔ ہلال کا عکس جو پانی میں نظر آرہا ہے ایسا معلوم ہورہا ہے کہ شب میں پریوں نے پانی میں کھیل و کھینچا تانی کی ہوگی۔ چنانچہ اس کشمکش میں ایک کنگن ٹوٹ گیا جس کا نصف پانی میں پڑا ہوا ہے اور نصف آسمان پردِکھ رہا ہے۔''
تاروں اور ہلال کی دوسری تشبیہ۔معّری:
| كأنّ اللّيلَ حارَبَها ففِيهِ | هِلالٌ مِثْل ما انعَطَفَ السّنانُ |
| ومِن أُمّ النّجُومِ عليه دِرْعٌ | يُحاذِرُ أن يُمَزّقَها الطّعَانُ |
| وقد بَسَطَتْ إلى الغَرْبِ الثرَيّا | يداً غُلقَتْ بأنْمُلِهَا الرّهانُ |
| كأنّ يَمِينَها سَرَقَتْكَ شيئاً | ومَقْطوعٌ على السَّرَقِ البَنانُ |
''معلوم ہوتا ہے کہ رات او رہمارے ممدوح کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگئی تھی۔ اب یہ ہلال کسی کے نیزہ کا مڑا ہواٹکڑا معلوم ہوتا ہے یہ کہکشاں کے تارے نہیں ہیں بلکہ رات کاذرہ بکتر ہے اور رات بہت ڈر رہی ہے کہ اس کا یہ زرہ بکتر نیزہ کی انی سے پھٹ نہ جائے۔ ثریا مغرب کی طرف اپنا وہ ہاتھ بڑھاتا ہے جس کی انگلیاں کٹ گئی ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ چرایا تھا جس کی سزا میں اس کی انگلیاں کاٹی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ ثریا کے عربوں کے پاس دو ہاتھ ہیں ایک حنائی اور ایک کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ کف خضیب۔ کف جذما۔''
ایک سانولی کی تعریف، شریف رضی متوفی 406ھ
أحبك یالون الشباب لأنني ........ رأیتکما في القلب والعین توأما
سکنت سواد القلب إن کنت شبھه ........ فلم هدر من عز من القلب منکما
''اے رنگ جوانی مجھے تجھ سے عشق ہے کیونکہ دل میں بھی یہی رنگ آتا ہے او رآنکھوں میں بھی یہی رنگ ملتا ہے۔ سواد قلب میں تو آکر بسی ہے کیونکہ تو اس کے مشابہ ہے، اب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ دونوں میں سے دل کون ہے۔''
جھپکنا ۔معّری :
یسرع اللمح في أحرار کما تسرع ........ في اللمح مقلة الغضبان
''سرخی لیے ہوئے تارا بہت جلد جلد جھپکتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی غضبناک شخص کی آنکھ ہے۔''
عاشق کا کھنڈر پر سونچتے کھڑے ہونا۔ (متنبّی)
بَليتُ بِلى الأطْلالِ إنْ لم أقِفْ بها وُقوفَ شَحيحٍ ضاعَ في التُّرْبِ خاتمُهْ
کھنڈروں کی طرح مجھے بھی تباہی نصیب ہو اگر وہاں پراس بخیل کے مانند جس کی مٹی میں انگوٹھی گم ہوگئی ہو، اور سونچتا ڈھونڈھتا کھڑا رہ کر یادرفتگان میں مصروف نہ ہوجاؤں۔''
قوس قزح، سیف الدولہ
و ساق صبيح للصبوح دعوتـــــه فقـــــام و في أجفانــــه سنــة الغمــــض
و قد نشرت أيدي الجنوب مطارفـاًَ على الجود كناً و الحواشي على الأرض
يطوف بكاسـات العقـــار كأنجـــــم فمــــن بين منقض علينـــــا و منفـــض
يطرزها قوس الغمــــام بأصفــــــر على أحمر في أخضـــــر تحت مبيـــض
كأذيال خــــود أقبلت في غلائـــــــل مصبغـــة و البعض أقصـــــر من بعض
''ایک خوبصورت ساقی کو میں نے بلایا او روہ کھڑا ہوا حالانکہ اس کی آنکھوں میں غنودگی سی مستی تھی، دور شراب چل رہا تھا اور ساغر مانند تاروں کے نظر آرہے تھے جو آسمان سے یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہے تھے۔ باد جنوب نے فضا پرکالی چادریں پھیلا دی تھیں جس کے حاشیے زمین پر لٹک رہے تھے۔ قوس کی شکل میں ابر نے اسے سنوارا تھا۔چادر کے کنارے پر قدرت نے سرخ سفید، سبز رنگ کی بیلیں ٹانک دی ہیں گویاکہ ایک عروس نازنین نے اون کے رنگین پیراہن پہن لیے ہیں جن کے دامن علی الترتیب ایک دوسرے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے ہیں۔''
شراب۔
رق الزجاج ورقت الخمر ........ فتشابھا فتشا کل الأمر
فکأنھا خمر ولا قدح ........ وکأنھا قدح ولا خمر
''شیشہ جام بھی رقیق اور شراب بھی رقیق دونوں بالکل مشابہ پش گویا کہ شراب ہے او رجام غائب یا صرف جام بلاشراب۔''
چمن میں نسیم کا چلنا۔ ذہبی (یوسف )متوفی680ھ
ھلم یاصاح إلی روضة ........ یجلوبھا العاني صداھمه
نسیمھا یعثر في ذیله ........ وزھرھا فیضحك في کمه
''دوست چلو ایک چمن میں تو آؤ جہاں مصیبت زدہ کے ہم و غم کا زنگ دور ہو طبیعت صاف ہوجاتی ہے۔ اس چمن کی باد صبا اپنے ہی دامن میں اُلجھ کر رہ جاتی ہے جس سے پھول اپنے شگوفہ (آستین) میں مسکرا دیتا ہے۔''
موسم بہار۔ بختری ابوعبادۃ المتوفی 248ھ
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا
من الحسن حتى كــاد ان يتكلما
وقد نبه النيروز في غسق الدجى
اوائل ورد كن بالأمــس نومـا
يفتقهـا بـرد الندى فكأنـــه
يبـث حديثـا كان قبل مكتمــا
فمن شجر رد الربيــع لباسـه
عليه كمـا نشـرت وشيا منمنما
ورق نسيم الريح حتـى حسبتـه
يجيء بأنفـاس الأحبـة نعمــا
''موسم بہار کی آمد ہے جو ہنستے ہوئے اپن ےحسن کے غرور سے بڑے ناز وانداز سے چل رہی ہے او رایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب قریب ہےکہ بول اُٹھے نیروز نے رات کی تاریکی میں گل کی پہلی صف کو بیدار کردیا جو کل تک نیند کا مزہ لے رہے تھے۔ شبنم کی ٹھنڈک انہیں کھلا رہی ہے گویا کہ وہ اس کو کوئی پوشیدہ راز کی بات کہہ رہی ہے جس سے وہ خوش ہورہے ہیں بادصبا اتنی نازک اور لطیف ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دوستوں کے سانس پرمشتمل ہے۔''
اولاد۔ معلی۔ ہارون الرشید کے زمانہ میں مصر میں رہتا تھا۔
وإنما أولاد نا بینا ........ أکبادنا تمشي علی الأرض
إن ھبت الریح علی بعضھم ........ أشفقت العین من الغمض
''بے شک ہماری اولاد ہمارے درمیان ہمارے لخت جگر ہیں جو زمین پرچلتے پھرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو ہوا بھی مس کرے تو آنکھ کے لیے بوجہ شفقت نیند حرام ہوجاتی ہے۔''
فطرت کی نیرنگیاں ۔ابن سہیل اندلسی المتوفی 649ھ
الأرضُ قد لبِستْ رِداءً أخضَرا و الطلُّ ينثرُ في رباها جوهرا
هاجتْ فخِلتُ الزَّهرَ كافوراً بها وحسِبتُ فيها التُّربَ مِسكاً أذفَرا
و كأنَّ سوسنها يصافحُ وردها ثغرٌ يقبلُ منه خداً أحمرا
والنهرُ ما بينَ الرّياضِ تخالُه سَيفاً تَعَلّقَ في نِجَادٍ أخضَرا
و جرت بصفحته الصبا فحسبتها كَفّاً تُنَمِّقُ في الصَّحيفة ِ أسطُرا
وكأنّه إذ لاحَ ناصِعُ فِضّة ٍ جعلتهُ كفُّ الشمسِ تبراً أصفرا
أو كالخدودِ بدَتْ لَنَا مُبيَضَّة ً فارْتَدَّ بالخَجَلِ البياضُ معصْفرا
والطّيرُ قد قامت عليه خَطِيبَة ً لم تتخذْ إلاَّ الأراكة َ منبرا
''زمین سبز پوش ہے جس پر شبنم نےجواہرات بکھیر دیئے ہیں۔ یہ منظر ولولہ خیز ہے۔ پھول کافور کا مزہ دے رہے ہیں اور وہاں کی مٹی سے تیز مشک کی بُو آری ہے۔ گل سوسن گلاب سے مصافحہ کررہا ہے یا یوں کہیئے گل کے گلابی رخسارہ پر کسی کے سفید دانت گستاخی کررہے ہیں چمنون کے درمیان سے نہریں گزرتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے سبز حمائل میں تلوار داخل ہورہی ہے، اس چمن کےنواح اطراف میں تیلے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ صحیفہ فطرت میں ایک دست قدرت صناعی کے نمونوں کی طرح سطر لکھ رہی ہے، پرندوں کی تصویریں پھلوں کے درخت کو منبر بناتے ہوئے اپنی تقریر دلپذیر میں مصروف ہیں۔''
فطرت ۔ ابن الساعاتی :
والطل في سلك الغصون کلؤلؤ ........ رطب یصافحه النسیم فیسقط
الطیر تقرأ والغدیر صحیفة ........ والریح تکتب والغمام ینقط
''شبنم ڈالیوں کی مالا میں موتیوں کا نظارہ پیش کرتی ہے جو باد نسیم کے آنے او رمصافحہ کرنے میں زمین پر گرے ہیں۔بوندیں پڑ رہی ہیں اور تالاب صحیفہ قدرت کا کام دے رہا ہے ۔ ہوا لکھ رہی ہے اور ابرنقطے دے رہا ہے۔''
پہیلیاں ۔ تربوز۔ ابن التعاویذی :
حلوة الریق حلال ........ دمه في کل مله
نصفھا بدر ران قسمتھا ........ صادت أھله
''شیریں لب ہے اس کا خون ہر فلت میں جائز ہے ۔نصف کرو تو چاند او رٹکڑے کرو تو ہلال ''
ترازو ۔امیر تمیم :
وما یصدق بلا نطق ولا فھم ........ بواصین مبین صامت حکم
یقضي ولیس له سمع ولا بصر ........ وترتضیه الوریٰ طرا إذا اختصموا
''ایک سچا ہے جو بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، نیک ہے، امین ہے، خاموش ہے، لیکن فیصلہ کن حکم سناتا ہے۔ فیصلہ کرتا ہے لیکن نہ اس کا کان ہے نہ آنکھ پھر لطف یہ ہے دنیا اس کے فیصلہ کو منظور کرتی ہے۔''
کتاب :
لنا جلساء لانمل حدیثھم ........ الباء مامونون غیبا و مشھدا
''ہمارے چند ہم نشین ہیں جن کی باتوں سے طبیعت اکتاتی ہی نہیں ۔ عقلمند ہیں۔ ایسے دوست ہیں جو غیاب و حضور میں غیبت نہیں کرتے۔''
قفل ۔ البھا۔ زہیر 656ھ
وأسود عادا لخل البرد جسمه ........ وما زال من أوصافه الحرص والمنع
وأعجب شيء کونه الدھر حارسا ........ ولیس له عین و لیس له سمع
''ایک سیاہ برہنہ لاغر بدن اور جس کا بڑا اصول کسی کونہ دینا ہے۔ سب سے تعجب خیز یہ ہے کہ ہمیشہ وہ نگہبانی کی خدمت انجام دیتا ہے لیکن نہ اس کا کان ہے نہ آنکھ۔''
حکیمانہ کلام : جاہلیت میں اگرچہ بظاہر حکیمانہ کلام خال خال ملتا ہے لیکن جو کچھ بھی ہے نہایت مادہ مؤثر اور واقعات کی تشریح ہوتی ہے۔
طرفہ بن عبد۔ عزیزوں کا ظلم:
وظلم ذوي القربیٰ أشد مضاضة ........ علی المرء من وقع الحسام المھند
''قرابت والوں کا ظلم انسان کے لیے تیغ ہندی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے ۔زمانہ خود مؤدب و معلم ہے۔''
ستبدي لك الأیام ما کنت جاھلا ........ ویأتیك بالأخبار من لم تزود
صحبت کا اثر :
عن المرء لا تسئل وسل عن قرینه ........ فکل قرین بالمقارن یقتدي
''آدمی کا کیریکٹر معلوم کرنا ہے تو وہ کن کن کے ساتھ رہتا ہے معلوم کرو، دوست کا کیریکٹر ہی انسان کے کیریکٹر کا آئینہ ہوسکتا ہے۔''
زہیر۔ بڑھاپے سے بیزاری :
سأمت تکالیف الحیاة ومن یعش ........ ثما نین حولا لا أبالك یسأم
''زندگی کی تکالیف سےبیزار ہوگیا ہوں اور جو شخص اسی سال کی عمر کا ہو اس کوبیزار ہونا ہی چاہیے۔''
آئندہ کی خبر نہیں:
وَأَعلَمُ عِلمَ اليَومِ وَالأَمسِ قَبلَهُ, وَلَكِنَّني عَن عِلمِ ما في غَدٍ
موت کانشانہ لگانا:
رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ *** تُمِـتْهُ وَمَنْ تُخْطِىء يُعَمَّـرْ فَيَهْـرَمِ
دنیا سازی کی ضرورت:
ومن لا یصانع في أمور کثیرة ........ یضرس بأنیاب ویوطأ بمنسم
عزت کی حفاظت کے لیے پیشہ خرچنا:
من یجعل المعروف من دون عرضه ........ یفرہ من لا یتق الشتم یشتم
غیر مستحق پر احسان کرنا:
ومن یجعل المعروف في غیر أھله ........ یکن حمده زما عليه ویندم
اپنے ناموس کی حفاظت کرنا:
ومن لا یذد عن حوضه بسلاحه ........ يھلك مرومن لا یظلم الناس یظلم
خود اپنی آپ عزت کرنا:
ومن یغترب یحسب عدوا صدیقه ........ ومن لایکرم نفسه لا یکرم
انسان کے خصائل چھپ نہیں سکتے:
ومھماتکن عند امرئ من خلیقة ........ وإن خالھا یخفی علی الناس یعلم
اسلام کے بعد تو اخلاقی او رحکیمانہ شاعری کوبہت عروج ہوا۔کیونکہ اسلام نے خود بہترین اخلاق کادرس دیا اس کے بعد عام فلسفہ او راخلاقی کتابوں کے ترجمے ہوئے ۔ مختلف نظریے رائج ہوئے۔اس سے شاعری بھی محروم نہ رہ سکی۔
شاعر: ومن یك ذافم مرمریض ........ یجد مرّابه الماء الزلالا
بحتری: زخم کے فساد کا سبب طبیب کی بے پروائی ہے۔
إذا ما الجرح دم علی فساد ........ تبین فيه إھمال الطبیب
دیگر: جس کام کے توڑنے پر مخالف کمربستہ ہو وہ پورا نہ ہوگا۔
متی یبلغ البنیان یوم تمامه ........ إذا کنت تبنیه و غیرك یھدم
متنبّی: زہر سے بچنے کا علاج زہر نہین ہے۔
إلَيْكِ فإنّي لَسْتُ ممّنْ إذا اتّقَى, عِضاضَ الأفاعي نامَ فوقَ العقارِبِ.
متنبّی: بعض وقت خفگی کا نتیجہ مفید ہوتا ہے۔
لعل عتبك محمود عواقبه ........ وربما صحت الأجساد بالعلل
''شاید کہ تیری ناراضگی کا انجام بہتر ہو۔ اکثر بیماری باعث شفا ہوجاتی ہے۔''
بحتری: بغیر صحیح راستہ اختیار کیے منزل مقصود تک رسائی نہیں ہوسکتی۔
ترجو النجاة ولم تسلك مسالکھا ........ إن السفینة لا تجري علی الیبس
''بغیر صحیح راستہ اختیار کیےنجات کی اُمید کرتا ہے۔ خشکی پر جہاز نہیں چل سکتا۔''
ایک اسدی۔ دنیا میں نام پیدا کرنا آسان نہیں۔
لا تحسب المجد تمرا أنت آکله ........ لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا
''بزرگی کھجور نہیں کہ مزہ سے کھاؤ گے جب تک ایلوا نہ چاٹو بزرگی حاصل کرنا مشکل ہے۔''
لامیۃ العجم۔ سفر وسیلہ ظفر ہے (مؤید الدین الاستاد العمید ابواسماعیل الحسین بن محمد الطغرائی المقتول 513ھ)
إن العلا حدثتني وھي صادقة ........ فیما تحدث العزفي النقل
لوکان في شرف الماوی بلوغ مني ........ لم یبرح الشمس یوما دارة الحمل
''بلندیوں نے مجھے یہ حدیث سنائی او ربلندیاں بالکل سچ کہتی ہیں کہ عزت نقل و حرکت میں ہے اگرایک ہی جگہ رہنے سے شرف حاصل ہوسکتا تو آفتاب برج حمل کو کبھی نہ چھوڑتا۔''
اہل علم کے ساتھ زمانہ کا بُرا سلوک۔
أھبت بالحظ لو نادیت مستمعا ........ والحظ عني في الجھال في شغل
''میں نے خوش بختی کو آواز دی کاش کہ وہ سنتی اس کو فرصت کہاں وہ تو جاہلوں کے پاس مصروف ہے۔''
اُمیدپردنیا پرقائم ہے۔
أعلل النفس بالآ مال أرقبھا ........ ما أضیق العیش لولا فسحة الأمل
''اُمیدوں سے جی بہلاتا ہوں۔ واقعی اگر اُمیدوں کا سہارا نہ ہوتا تو دنیا کتنی تنگ معلوم ہوتی۔''
کمینوں کی حکومت۔
ماکنت أوثرأن یمتدبي زمني ........ حتی أری دولة الأوغا دوالسفل
''مجھے یہ خواہش نہیں کہ میں اور دن دنیا میں زندہ رہ کر کمینوں کی حکومت کے دن دیکھوں۔''
نااہلوں کی قابل افراد کے عوض قدردانی۔
تقدمتني أناس کان شوطھم ........ وراء خطوي ولوأمشي علی مھل
فإن علاني من دوني فلا عجب ........ لي أسوة بالخطاط الشمس عن زحل
''ایسے لوگ جن کی تیز رفتاری بھی میری معمولی چال کا مقابلہ نہیں کرتی، مجھ سے آگے نکل گئے اگر مجھ سے کم درجہ کے لوگ مجھ سے اعلیٰ مراتب حاصل کرلیں تو کیا تعجب ہے مجھے زحل کے بلند اور آفتاب کے نیچے ہونے سے اچھا سبق حاصل ہوسکتا ہے۔''
کسی شخص پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔
أعدی عدوي أدنی من وقفت به ........ فحاذ رالناس و أصبحھم علی دخل
فأنا رجل الدنیاوواحدھا ........ من لایقول في الدنیا علی رجل
''سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جس پر تو پورا بھروسہ کرتا ہے اس لیے ہمیشہ محتاج زندگی بسر کر۔ بے شک دنیا میں بے نظیر آدمی وہی ہے جو دنیا میں کسی پر بھروسہ نہ کرے۔''
دنیا کی بے ثباتی۔
نرجو البقاء بدار لا ثبات لھا ........ فھل سمعت بظل غیر منتقل
''ایسے گھر میں بقا کی امید کرتا ہے جو فانی ہے کیا سایہ بھی قائم رہتا ہے۔''
شریفانہ اخلاق۔ ابوالعتاہیۃ
أحبَ الفتى ينفي الفواحش سمعه ... كأنَّ به عن كل فاحشة وفرا
سليمُ دواعي الصدر لا باسطاً أذىً ... ولا مانعاً خيراً ولا قائلاً هجرا
إذا شئت أن تدعى كريماً مكرماً ... أديباً ظريفاً عاقلاً ماجداً حرا
إذا ما بدتْ من صاحبٍ لك زلةٌ ... فكنْ أنت محتالاً لزلتهِ عذرا
''میں ایسے جوان مرد سے محبت کرتا ہوں جس کے کان بُری باتوں سے آشنا نہیں گویا کہ بُری باتوں کے لیے جس کے کان بہرے ہیں۔ اس کے سینہ میں کسی کے متعلق کوئی خلش نہیں نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے نہ اچھے کام سے ہاتھ روکتا ہے اور نہ فضول بکواس کرتا ہے اگر تو چاہے تو دنیا تجھے کریم،معزز، ادیب، ظریف،عقلمند،بزرگ اور شریف مان لے تو جب کبھی کسی سے لغزش ہوجائے تو ان کے لیے تو خود ہی عذر تلاش کرنے کی کوشش کر (تاکہ تیرا حلقہ احباب وسیع ہوتا جائے اور تیری ہر دلعزیزی بڑھتی جائے۔''
شوقی۔ نوجوانوں سے خطاب:
يا شَبابَ الغَدِ وَاِبنايَ الفِدىلَكُمُ أَكرِم وَأَعزِز بِالفِداء
عَصرُكُم حُرٌّ وَمُستَقبَلُكُمفي يَمينِ اللَهِ خَيرِ الأُمَناء
| لا تَقولوا حَطَّنا الدَهرُ فَما | هُوَ إِلّا مِن خَيالِ الشُعَراء |
| هَل عَلِمتُم أُمَّةً في جَهلِها | ظَهَرَت في المَجدِ حَسناءَ الرِداء |
فَخُذوا العِلمَ عَلى أَعلامِهِوَاِطلُبوا الحِكمَةَ عِندَ الحُكَماء
وَاِحكُموا الدُنيا بِسُلطانٍ فَماخُلِقَت نَضرَتُها لِلضُعَفاء
''اے مستقبل کے نوجوانو! میرے بیٹے تم پر فدا ۔ تمہارا زمانہ آزادی کا زمانہ ہے اور تمہارا مستقبل مبارک و میمون ہے۔ یہ مت کہو کہ ہم کو زمانہ نے پست کردیا ہے۔ یہ صرف شاعروں کا خیال ہے۔ کیا ایسی قوم سے واقف ہو جس نےباوجود جاہل رہنے کے ترقی کی ہو۔ مشاہیر علماء سے علم حاصل کرو او رحکیموں سے حکمت سیکھو۔ دنیا پراقتدار اعلیٰ کے ساتھ حکومت کرو۔ دنیا کی تازگی سے مستفید ہونے کا حق ضعیفوں کو نہیں ہے۔''
بازیچہ اطفال سے دنیا میرے آگے ۔شوقی :
أناس کما تدري و دنیا بحالھا ........ ودھررخی تارة وعسیر
وأحول خلق غابر متجدد ........تشابھا فیھا أول وأخیر
تمرتباعا في الحیاة کأنھا ........ ملا عب لا ترجی لھن ستور
وحرص علی الدنیا و میل مع الھوی ........ وغش وإفك في الحیاة و زور
''لوگوں کے حالت سے تم واقف ہو۔ دنیا بھی اپنی حالت پرقائم ہے۔ ایک وقت تنگی کا آنا ہے ایک وقت فراخی کا۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ایک حالت گزر جاتی اور دوسری پیدا ہوتی ہے۔پے درپے زندگی کے وقائع اسی طرح ہوتےرہتے ہیں گویا کہ یہ تماشے ہیں جن کے لیے پردہ سنیما کی ضرورت نہیں۔ دنیا پرحرص، خواہشات کی اتباع،دھوکا دینا اور جھوٹ ہی زندگی کی کائنات ہے۔''
متنبّی :
إذا أنت أکرمت الکریم ملکته ........ وإن أنت أکرمت اللئیم تمردا
ووضع الندی في موضع السیف بالعلاء ........ مضر کو ضع السیف في موضع الندی
''اگر تو شریف کی عزت افزائی کرے گا تو وہ تیرا ممنون ہوکر اطاعت بردار ہوجائے گا اور اگر کسی کمینہ کی حوصلہ افزائی کی تو وہ سرکش ہوجائے گا۔ جہاں تلوار کی ضرورت ہے وہاں حلم کا استعمال اتنا ہی مضر ہے جتنا کہ حلم کے موقع پر سختی و تلوار کا استعمال۔''
اخلاق۔ صالح بن عبدالقدوس (مہدی نے اس کو الحاد کے الزام پر قتل کیا)
أدّ الأمانة ، والخيانةَ فاجتنـب ,, واعـدل ولا تظلـم يطيـب المكسـب
واحذر من المظلوم سهمـاً صائبـاً ,, واعلـم بـأن دُعـاءه لا يُحجـب
وإذا أصابك في زَمانك شدّة ,, وأصابـك الخطـب الكريـه الأصعـب
فادع لرَبك إنـه أدنـى لمـنْ ,, يدعـوه مـن حَبـل الوريـد وأقـرب
واحذر مؤاخاة الدّنـي لأنـه ,, يعـدي كمايعـدي الصحيـح الأجـرب
واختر صديقك واصطفيه تفاخراً ,, إن القَريـن إلـى المقـارنِ يُنسـب
ودع الكذوبَ ولا يكنْ لكَ صاحباً ,, إن الكذوبَ لبئـس خـلاً يصحـب
وذر الحسود وإن تقادم عَهده ,, فالحقـد بـاق فـي الصـدورِ مغيَّـب
واحفظ لِسانك واحترز من لفظـه ,, فالمـرء يسلـم باللسـان ويعطَـب
وزن الكلام إذا نطقـت ولا تكـن ,, ثرثـارةً فـي كـلّ نـاد تخطـب
والسرّ فاكتمـه ولا تنطـق بـه ,, فهـو الأسيـر لديـك إذ لا يَنشـب
واحرص على حفظ القلوب من الأذى ,, فرجُوعها بعد التنافر يصعـب
إن القلـوبَ إذا تنافـر ودهـا ,, شبـه الزجاجـة كسرهـا لا يشعـب
''امانت کو ادا کر اور خیانت سے اجتناب کر، عدل کو لازم رکھ، کامیاب رہے گا۔ مظلوم کی دعا کے تیرسے بہت ہوشیار رہ کیونکہ اس کی دعا کو عرش تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں۔ ذلیل کی دوستی سے بچتا رہ کیونکہ وہ خارش کی طرح متعدی ہے۔ کبھی جھوٹے سے دوستی نہ کر جھوٹا بہت ہی خراب دوست ثابت ہوا ہے۔ زبان پر قابو رکھ او ربولنے میں احتیاط رکھ۔ آدمی زبان ہی سے سلامت رہتا ہے اور اسی سے تباہ ہوتا ہے۔ تو ل پھر بول۔ فضول گو مت بن جیسا خیال میں آیا بک دیا۔ مردم آزادی سے بہت بچتا رہ۔ جو دل تجھ سے ناراض ہو پھر اس کا مننا مشکل ہے۔ دل بے شک شکررنجی کے نقطہ نظرسے کانچ ہے جہان اس پر بال آیا تو پھر اس کا جڑنا ناممکن ہے۔''
عین الرضا۔ عبداللہ بن معاویہ بن عبد بن جعفر المتوفی 132ھ
وعین الرضي من کل عیب کلیلة ........ کان عین السخط تبدي المساویا
'' رضا مند کی آنکھ ہر عیب سے کند ہے جیسے کہ نارضامندی کی آنکھ بُرائیوں کا اظہار کرتی رہتی ہے۔''
زندگی ایک اسٹیج ہے۔
النوم موت أصغر ........ والموت نوم أکبر
دنیا تشابه ملعیا ........ واللیل ستو یستر
جند ھناك وسوقه ........ رمتوج و مسخر
فإذا طرحت ثیابھم ........ ساوی الأعزالأحقر
''نیند چھوٹی موت ہے او رموت ایک بڑی نیند کا نام ہے۔دنیا ایک تماشا گاہ ہے اور زمانہ ایک پردہ تماشا ہے۔ کوئی فوجی ہے کوئی عہدہ دار ہے ۔ کوئی صاحب تاج ہے اور کوئی محکوم ہے۔اگر عریاں حقیقت دیکھیں تو نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا۔''
بستی۔ ابوالفتح المتوفی 400ھ
زيادة المرء في دنياه نقصان = وربحه غير محض الخير خسران
وكل وجدان حظٍ لا ثبات له = فإنّ معناه في التحقيق فقدان
يا عامراً لخراب الدار مجتهداً = بالله هل لخراب الدار عمران
ويا حريصاً على الأموال تجمعها = أنسيت أن سرور المال أحزان
زع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها = فصفوها كدرٌ والوصل هجران
وأرعِ سمعك أمثالاً أفصلها = كما يفصل ياقوت ومرجان
أحسن إلى الناس تسعبد قلوبهم = فطال ما استعبد الإنسان إحسان
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته = أتطلب الربح مما فيه خسران
أقبل على النفس واستكمل فضائلها = فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
دع التكاسل في الخيرات تطلبها = فليس يسعد بالخيرات كسلان
''انسان دنیا میں جتنی ترقی کررہا ہے دراصل وہ اس کا نقصان ہورہا ہے کیونکہ بجز افعال نیک کے باقی ہر قسم کا فائدہ ،نقصان ہی نقصان ہے۔اے وہ شخص جو دنیا کے ویرانے کو آباد کررہا ہے ۔کیاعمر کے تباہ شدہ حصہ کی بھی آبادی کابھی خیال ہے۔ دنیااور دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ بظاہر، صفائی کدورت اور وصال کا نتیجہ فراقی کا پیغام ہے۔لوگوں کی طرف احسان کرو،وہ تیرے بے دام غلام بن جائیں گے۔ ہمیشہ سے انسان احسان کا غلام ہے۔نفس پر توجہ کر اور اس کے فضائل مکمل کرنے کی کوشش کر۔ کیونکہ تو نفس سے انسان ہے نہ کہ خاکی جسم سے۔ خدا کے رشتہ کو پکڑ رکھ کیونکہ وہ ایسا سہارا ہے جب دوسرے سہارے کام نہ آئیں گے۔ وہ کام آئے گا۔ نیک کاموں میں سستی چھوڑ دے۔ سست آدمی کبھی نیکی حاصل نہیں کرسکتا۔''
ابن قلاقش المتوفی 565ھ
| سافِرْ إذا حاولتَ قَدْرا | سارَ الهلالُ فصارَ بَدرا |
| والماءُ يكسِبُ ما جرى | طيباً ويخْبُثُ ما استقرا |
| وبنقلة الدُرَرِ النفي | سةِ بُدِّلتْ بالبحرِ نَحْرا |
| وَصْلاً إن امتلأتْ يدا | كَ فإن هُما خلَتا فهجْرا |
| فالبدرُ أنفقَ نورَه | لما بَدا ثمّ استَسَرّا |
''اگر تجھے قدر دانی کی خواہش ہے تو سفر کر ہلال نے سفر کیا ماہ کا مل بن گیا۔ پانی جب تک بہتا رہا اچھا رہا اور اگر ایک جگہ جمع رہا تو متعفن ہوجاتا ہے ۔ نفیس موتی نے وطن کو چھوڑا تو سمندر کی تہ کی بجائے سینہ پر رونق افروز ہوا۔''
حاشیہ
۔اس مضمون کےلیے مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کیا گیاہے۔العمدہ لابن رشیق، شعر العجم از علامہ شبلی ، الوسیط۔تالیف شیخ احمد سکندری و شیخ مصطفیٰ عنانی۔کتاب حیواۃ الحیوان للدمیری۔ دیوان امیر تمیم بن المعز فاطمی۔ دیوان معری۔ دیوان متنبّی۔السبع المعلقات۔ مقدمہ دیوان حالی۔