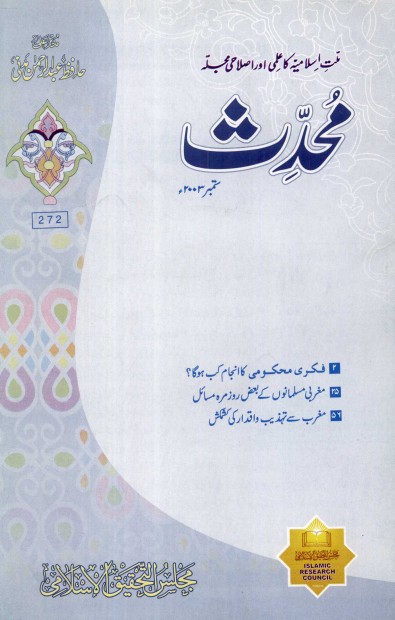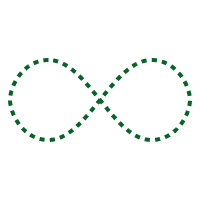فکری محکومی کا انجام کب ہوگا؟
بر صغیر پاک وہند کے مسلمانوں کے لئے علیحدہ ریاست کے قیام کا مقصد عظیم ہی یہ تھا کہ الگ سے ایک خطہ زمین مسلمانوں کو مل جائے جہاں وہ اپنے تہذیب وتمدن کو از سر نو قائم کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے گزار سکیں۔
آج جب ہم ۵۶برس کے بعد قیامِ پاکستان کے مقاصد اور پاکستانی معاشرے کی نہج کا باہمی موازنہ کرتے ہیں تو سخت پریشانی اور اُلجھن ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک خواب تھا جو ریزہ ریزہ ہوگیا ہے اور جس کی تعبیر اور تکمیل کا امکان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ انگریزوں کی سیاسی غلامی سے آزادی کے بعد ہماری ذہنی وفکری محکومی نہ صرف بدستور چلی آئی ہے بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔
افسوس ناک امر یہ ہے کہ اس ذ ہنی وفکری محکومی کے خاتمے کے لئے منظم شعوری جدوجہد کی بات تو کیا، سرے سے اس فکری محکومی کا احساس ہی مفقود ہوتا جارہا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک صورت یہ ہوگئی ہے کہ ہمارے اندر اس ثقافتی وفکری غلامی کی طرف پسندیدگی اور چاہت کا شدید میلان پیدا ہورہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے اندر اپنے تہذیب وتمدن کے متعلق حقارت آمیز جذبات بھی تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ ثقافتی استعمار کی یہ بدترین صورت ہے کہ جس کا ہم پاکستانی قوم کے طور پر بحیثیت ِاجتماعی شکار ہیں۔ ہماری تہذیبی وسماجی اقدار اس تیزی سے بدل رہی ہیں کہ ہمیں اپنا قومی چہرہ اور تشخص پہچاننے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دیہاتوں میں ابھی صورتِ حال اس قدر سنگین نہیں ہے، لیکن ہمارے شہروں کا تمدن تو بہت حد تک بدل چکا ہے !! ہمیں اس تہذیبی مظہر کا شعوری طور پر تجزیہ کرنا چاہئے۔ آخر ہماری اس فکری محکومی اور ثقافتی مرعوبیت کے اسباب کیا ہیں؟
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو تہذیبوں اور قوموں کا سیاسی سطح پر تصادم ہوتا ہے تو پہلے عرصے میں غالب قوم محکوم قوم پر اپنا سیاسی اقتدار مستحکم کرنے کے لئے تہذیبی تسلط قائم کرنے کی سر توڑ کوشش کرتی ہے اور محکوم قوم اس استیلا کے خلاف شدید مزاحمت کرتی ہے، اسے اجنبی کلچر کی برتری کا احساس نہیں ہوتا بلکہ جارح کلچر سے اپنے ثقافتی اور تہذیبی ڈھانچے کو محفوظ رکھنے کا احساس شدت سے اجاگر ہوتا ہے، اور اس کے خلاف نفرت کے جذبات شدت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس اولین مرحلے میں حاکم اور محکوم قوموں کے درمیان تہذیبی اختلاط زیادہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب غالب قوم کا سیاسی اقتدار طول اختیار کرتا جاتا ہے اور وہ تمام سیاسی ومعاشی اداروں اور ملک کے تمام تر وسائل پر قابض ہو جاتی ہے اور محکوم قوم کو معاشی استحصال اور جبر کے آہنی شکنجے میں کس لیتی ہے تو پھر محکوم قوم کے کچھ طبقات حوصلہ ہار جاتے ہیں اور آنے والے حکمرانوں کو ناگزیر حقیقت سمجھتے ہوئے ان سے سمجھوتہ کر لینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے دی گئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ ملازمتوں کا حصول ممکن ہو سکے، اسی طرح تہذیبی تصادم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ جہاں محکوم قوم کی غالب اکثریت اپنی تہذیبی وسماجی اقدار سے چمٹی رہتی ہے اور غالب قوم کو پہلے ہی کی طرف غاصب اور اجنبی سمجھتی ہے، البتہ ایک اقلیت حاکم قوم کے ساتھ اقتدار میں شراکت کی خواہش کے تابع اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتی ہے اور انہیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتی ہے۔
یہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو حکمران طبقے کی طرف سے دی گئی مراعات سے بھرپور استفادہ کرتا ہے اور ایک منزل آنے پر ان کے دست وبازو کی حیثیت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اپنا تعلق عوام الناس سے منقطع کرکے حکمران طبقے سے غیر مشروط وابستگی کی صورت میں جوڑ لیتا ہے۔ دو تین نسلوں کے بعد اس طبقے کی ذہنی ترقی اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ حاکم قوم کے کلچر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اسی کو پروان چڑھانے کے لئے مسلسل جدوجہد میں مصروف رہتا ہے۔ عوام کی اکثریت اس مراعات یافتہ طبقے کو استحصالی گروہ سمجھتی ہے اور اس سے متنفر رہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مراعات یافتہ طبقے اور اس کے حواریوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ملکی وسائل اور حکومتی اداروں پر اپنا تسلط اس طرح جمالیتے ہیں کہ عام افراد کے لئے ان سے تعاون کئے بغیر نہ تو ملازمتوں کا حصول ممکن رہ جاتا ہے اور نہ ہی معاشی میدان میں ترقی کے امکانات باقی رہ جاتے ہیں، اس لئے چار وناچار ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر حکومتی مشینری کا جبر واستبداد، حکومتی ذرائع ابلاغ کا جارحانہ پراپیگنڈہ، تعلیمی اداروں اور دیگر حکومتی شعبہ جات کے توسط سے حکومتی نقطہ نظر کی وسیع پیمانے پر تشہیر اچھے خاصے صاحب ِعقل افراد کی مقامی ثقافت سے وابستگی اور اس پر اعتماد کی چولوں کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ وہ شدید فکری اور تہذیبی کرب سے گزرنے کے بعد بالآخر غالب ثقافت کے سامنے نہ صرف ہتھیار ڈال دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنانے میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سے قوموں کے تہذیبی تصادم کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ بلکہ اسے تصادم کی بجائے 'ملاپ' کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ عملاً 'تصادم' ملاپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔اس دور کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ محکوم قوم کو اپنا تہذیب وتمدن اور طرزِ معاشرت، فکری منہاج اور سماجی اقدار دوسرے درجے کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور وہ انہیں اپنی ذہنی ومادّی ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ غالب قوم کی ثقافت اور ان کے تمام تہذیبی اداروں سے لگن اور چاہت کا گراف اونچا ہوجاتا ہے۔ ان کے قوانین، سماجی اقدار، سیاسی ادارے اور افراد ایک اعلیٰ اور برتر تہذیب کے مظہر دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں یہ احساس جاگزیں ہوجاتا ہے کہ ان کی غلامی کی اصل وجوہات ہی یہ ہیں کہ وہ اوران کی تہذیب وثقافت اور تمدن ایک فرسودہ، دقیانوسی اور رجعت پسندانہ معاشرے کی ثقافت کے مظاہر ہیں، جن کی ترویج ان کی ترقی کے لئے سم قاتل ہوگی۔ وہ مسلسل اس نفسیاتی خلجان میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنے اندر نشست وبرخاست، بول چال، لین دین، تحریر وتقریر، معاملات وتعلقات، لباس وپوشاک، کھیل وتفریح کے معاملے میں اپنے آپ کو آقائوں کے رنگ میں ڈھالنے کی شعوری وغیر شعوری کاوش کرتے رہتے ہیں۔ آقائوں کی محفل میں باریابی کو اپنے لئے باعث ِافتخار اور اعزاز سمجھتے ہیں اور ان کی طرف سے التفات ملنے پر پھولے نہیں سماتے۔ ان کی حصولِ جاہ وحشمت کی اس ساری جدوجہد کا زبردست المیہ یہ ہے کہ وہ 'فنا فی الاقا' کا مقام حاصل نہیں کر سکتے اور ان کے آقا ان کو اس سارے انجذاب اور تقلید کے باوجود ایک محکوم، گھٹیا اور غیر مہذب قوم کا فرد سمجھتے ہیں اور ہمیشہ ان سے غلاموں جیسا برتائوکرتے ہیں۔ آقا اپنی نسلی اور تہذیبی برتری میں محکوم قوم کو کسی بھی صورت میں شراکت کا حق نہیں دیتے، البتہ ان کو کچھ مراعات عطا کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ غالب قوم کے دست وبازو بن کر اس کے سیاسی اقتدار میں طوالت کا ذریعہ بنے رہیں۔
اس تہذیبی 'ملاپ' کے تیسرے دور میں بھی اجنبی ثقافت سے نفرت کا احساس بالکل ختم نہیں ہوجاتا۔ اب بھی ایک محدود طبقہ اس کو اپنانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اس کے خلاف برابر جدوجہد کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ تہذیبی غلامی کے کیا سنگین نتائج برآمد ہوں گے لیکن ان کی آواز 'صدا بہ صحرا' ثابت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ضمیر میں تہذیبی محکومی کا نشہ دوڑ چکا ہوتا ہے، وہ انہیں جاہل، خبطی اور رجعت پسند اور معاشرے کے ایک ناکام طبقے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ذرائع ابلاغ میں ان کی کھل کر تحقیر کی جاتی ہے، ان کا تمسخر اڑانے اور انہیں استہزا کا نشانہ بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا جاتا، نوجوان نسل کے دماغ میں یہ بات اُنڈیلی جاتی ہے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو اس قوم کو ترقی یافتہ اور خوشحال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جس کی ہٹ دھرمی اور غیر لچک دار رویے سے آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں کہ ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا کہیں بھی شمار نہیں!!
ذرا غور فرمائیے؛آج ہم غلامی کی کس منزل پر فائز ہیں، پہلی دوسری یا آخری منزل؟ اگر آپ کو پاکستانی قوم کے مقام کا تعین کرنے میں کسی قدر تذبذب کا سامنا ہے تو ہم آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں کہ ہم آج غلامی کی آخری منزل پر فائز ہیں اور اس میں استقامت کے حصول کے لئے اپنی ساری صلاحتیں کھپا رہے ہیں۔ ذہنی محکومی کی بدترین شکل وہ ہوتی ہے کہ جس کے اثرات معاشرے کے مراعات یافتہ محدود طبقے سے نکل کر معاشرے کے ادنیٰ طبقات کی عظیم اکثریت کے ذ ہنی ونفسیاتی ڈھانچے میں سرایت کر جائیں۔ صرف جدید تعلیم یافتہ، اہل ثروت، صنعت کار، بیورو کریٹس اور جاگیردار طبقے کی حالت میں تبدیلی کی بات ہوتی تو صورتحال اس قدر المناک اور کرب انگیز نہیں تھی۔ یہاں تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ادنیٰ طبقات جو ہر معاشرے میں بالا طبقات کے اثرات سے محفوظ رہتے ہوئے مقامی ثقافت کو اپنا کر اس کے تعمیری ارتقا کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، وہ بھی ذہنی محکومی کے سرطان سے محفوظ نہیں رہے۔ یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، عام مشاہدے کی بات ہے، جس کی تصدیق کے لئے کسی افلاطونی فلسفہ طرازی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
بر صغیر کے سماجی اور روایتی نظام نے بعض طبقوں اور پیشوں پر 'حقارت' کا ٹھپہ لگایا ہے حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہندوستانی معاشرے کے ان مطعون اور حقیر پیشوں سے منسلک خاندانوں کو 'کمی کمین' کا نام دیا جاتا ہے۔ فکری محکومیت کا یہ عالم ہے کہ اب وہ بھی اپنے کاروبار اور پیشوں کو فرنگی لبادہ اوڑھنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ آپ پورا شہر گھوم جائیے آپ کو کسی بھی 'نائی' یا حجام کا بورڈ دکھائی نہیں دے گا، ہر جگہ ' ہیرڈریسرز، باربرز اوربیوٹی پارلرز کے خوش رنگ بورڈ دکھائی دیں گے۔
پورے لاہور میں آپ کو 'درزی' کہیں نہیں ملے گا، البتہ 'ٹیلرز' ہر گلی کوچے میں کثرت سے مل جائیں گے۔ 'درزی' ایک ایسی جنس نایاب ہے جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں 'دھوبی' کا بورڈ دیکھنے کو نگاہیں ترس گئی ہیں، ہر طرف 'ڈرائی کلینرز' ہی پھیلے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں کوئی گویا؍ میراثی باقی نہیں رہا، ان کی جگہ آرٹسٹ، فنکار اور گلوکاروں نے لے لی ہے۔ کام کی اصلیت کوئی معنی نہیں رکھتی، یہاں تو نام چلتا ہے۔
اب ماشاء اللہ سب 'مشرف بہ مغرب' ہوگئے ہیں اور اپنے آپ کو عزت واحترام کا بجا طور پر مستحق سمجھتے ہیں۔ اب 'کپڑے کا بازار' اور 'بزاز' صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ پر مارکیٹس اور کلاتھ مرچنٹس اُگ آئے ہیں۔ آپ بھائی انگریزی زبان کے اعداد وشمار میں نہیں چکائیں گے تو دکاندار پر آپ کا تاثر ایک جاہل مطلق کاسا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کو انگریزی زبان نہیں آتی تو کم از کم دکاندار پر یہ راز منکشف نہ ہونے دیں کہ آپ اس سے یکسر نا بلد ہیں ورنہ آپ لمحوں میں اس کی نگاہوں میں گر سکتے ہیں۔ مال روڈ، لبرٹی مارکیٹ اور انار کلی کا سرسری جائزہ لیجئے، اگر ان میں گھومتے ہوئے آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کسی لندن کے بازار سے گذر رہے ہیں تو پھر یہ نقص آپ کے محسوسات میں ہے، ورنہ دکانداروں نے تو آپ کی سہولت کے لئے بے حد بلیغ انگریزی میں اپنی دکانوں کے ماتھوں پر بورڈ آویزاں کیے ہوئے ہیں۔
اب ذرا راہ چلتے ہوئے پرائیویٹ سکولوں کے بورڈوں پر نگاہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس عرق ریزی سے ہمارے ان 'ماہرین' تعلیم نے انگریزوں کے ناموں کو آپ کے ذوقِ مطالعہ کے لئے منتخب کیا ہے۔ برطانیہ میں تو کیمبرج، آکسفورڈ، گرامرجیسے ادارے شاید ایک ہی جگہ ہوں گے لیکن ہمارا کوئی شہر ان سے محروم نہیں ہے۔ سکولوں کو کامیابی سے چلانے کے لئے نمایاں طریق پر 'انگلش میڈیم' کو مشتہر کرنا ضروری ہے،کیونکہ ہماری قوم 'انگلش میڈیم' کے علاوہ کسی بھی سکول کو معیاری تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔اور اب تو سکولوں میں آکسفورڈ سے کم کسی نصاب کے ذریعے تحصیل علم کو بھی مشکوک خیال کیا جاتا ہے۔ ہرپبلک سکول میں امپورٹڈ نصابی کتب ہی تعلیمی معیار کی واحد ضمانت ہیں۔
شادی بیاہ کے متعلق عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں مقامی ثقافت اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہاں کے فائیو سٹار ہوٹلوں، شادی گھروں کا سروے کیجئے آپ کو انگریزی باجوں کے علاوہ دلہا موصوف بھی انگریزی لباس میں جلوہ افروز دکھائی دیں گے۔ معاملات طے کرتے وقت دیگر شرائط کے ساتھ لڑکی والوں کی طرف سے یہ شرط بھی عائد کی جاتی ہے کہ دولہا میاں کا کوٹ پتلون میں ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کے سماجی وقار کو شدید دھچکا لگے گا۔ کئی ایسے دولہائوں کی حالت ِزار پر ترس کھانے کو جی چاہتا ہے جنہیں شادی کے موقع پر پہلی مرتبہ انگریزی لباس زیب تن کرنے کے جان گسل مرحلے سے گذرنا پڑتا ہے، ان میں سے بعض تو جاہل مطلق ہوتے ہیں اور باراتیوں کی اکثریت ان کے اس 'علمی مرتبے' سے واقف بھی ہوتی ہے لیکن انہیں ان پابندیوں کا خیال بہر حال رکھنا پڑے گا ورنہ معاشرے میں ناک اونچی کیسے رہ سکے گی۔ ہمارے ایک دوست کے سسرال والوں نے یہ عجیب شرط بھی لگائی کہ دولہا کے ساتھ ساتھ باراتی بھی حتیٰ الامکان کوشش کریں کہ کوٹ پتلون پہن کر آئیں تاکہ محلے والوں پر رعب پڑ سکے۔
ہم 'ترقی' کی اس منزل پر فائز ہیں کہ ہماری قومی شاہراہوں پر ڈرائیور حضرات کے لئے ہدایات بھی بزبانِ انگریزی ہی درج کی جاتی ہیں۔ مری سے 'پتریاٹہ' جاتے ہوئے ہمیں عجیب اُلجھن کا سامنا کرنا پڑا، راستے میں رفتار آہستہ کرنے اور خطرناک موڑ کے متعلق نشاندہی کی سب ہدایات فصیح انگریزی زبان میں درج تھیں لیکن ہماری گاڑی کا ڈرائیور اَن پڑھ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے یہ شرط آخر کیوں نہ رکھی گئی کہ اس پر صرف انگریز خواتین وحضرات ہی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ہم سفر سے دریافت کیا کہ آخر اس سڑک پر اُردو میں ہدایات کیوں تحریر نہیں کی گئیں۔ ان کا جواب سن کر میں اپنے سوال پر شرمندہ ہوا، فرمایا :''آخر کچھ باہر کے ملکوں کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، ان کی سہولت کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔'' گویا مقامی ڈرائیوروں کو ان ہدایات کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے بین الاقوامی ہونے کا مصنوعی تاثر دینے کے مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔
ذرا قریبی 'اخبار سٹال' پر کچھ دیر رک کر آپ اخبارات اور رسائل کے ناموں کو غور سے پڑھئے، کئی ایسے اخبارات اور رسالہ جات پر آپ کی نگاہ پڑے گی، جو چھپتے تو اُردو میں ہیں لیکن ان کے نام انگریزی زبان میں رکھے گئے ہیں۔
ہماری قوم انگریزی تلفظ اور ادائیگی کے عشق میں مبتلا ہوتی جارہی ہے، انگریزی کے ساتھ ساتھ اگر اُردو کو بھی انگریزی کے لہجے میں ادا کریں گے، تو پھر آپ کے 'ماڈرن' ہونے پر شاید ہی کوئی شک کا اظہار کرے ۔چند منٹ اگر بعض نئے ریڈیو چینلز کو توجہ سے سنا جائے تو ایسی عجیب وغریب اُردو زبان سے آپ کا واسطہ پڑے گا جس کا کم وبیش ہردوسرا جملہ چند ایک انگریزی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر انگریزی الفاظ کو اُردو ترکیب میں بیان کرنے کے بعد، مسلسل انگریزی میں بولتے چلے جانا اب علمی مکالمہ کی پہچان بن چکا ہے۔میں اپنے ایک ملنے والے کا حوالہ دینا پسند کروں گا جو میٹرک کے امتحان میں چار دفعہ ناکام ہونے کے بعد کسی طریقے سے انگلینڈ جانے میں کامیاب ہوگئے، وہاں کافی عرصہ تک ایک ہوٹل میں برتن مانجھتے رہے، بعد میں 'ترقی' کی منازل طے کرتے کرتے بالآخر ٹیکسی ڈرائیور کے 'عہدئہ جلیلہ' پر فائز ہوگئے۔ کچھ عرصے کے بعد وطن واپس تشریف لائے، زبان سکیڑ سکیڑ کر اور لہجہ بنا بنا کر جب انگریزی میں گفتگو فرماتے تو مجلس میں موجود ہر شخص حسرت ویاس سے ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا اور دل ہی دل میں انگریزوں کا ممنونِ کرم بھی ہوتا کہ ان کے درمیان رہ کر پاکستان کا ایک ادنیٰ سا فرزند اس 'علمی کمال' اور لیاقت کے درجے پر فائز ہو گیا ہے۔ اور تو اور اچھے خاصے پڑھے لکھے حضرات اس سے مرعوب تھے۔
ہمارے ہاں انگریزی بول لینے کو ہی علم کی معراج سمجھا جانے لگا ہے اور ایک جاہل اور عالم فاضل کے درمیاں حد ِفاصل بھی انگریزی زبان ہی رہ گئی ہے۔ آپ ایم اے کرلیں تو کیا ہوا، جب تک انگریزی زبان میں قدرت حاصل نہیں ہوگی تو 'پڑھے لکھے جاہل' ہی رہیں گے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ذرا آپ گفتگو میں شستہ اُردو کی تراکیب، کچھ محاورات کا استعمال کریں گے، تو سننے والوں کا ذوقِ سماعت اور نازک طبعی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، فوراً ہی آپ پر 'مشکل گوئی' کا الزام لگا کر آپ کی ثقیل اُردو سننے سے معذرت طلب کی جائے گی، اگر خیر سے کہیں آپ انگریزی زبان کے کچھ رٹے رٹائے خوبصورت جملے گفتگو میں لے آئیں، تو آپ کی بات بے حد خشوع وخضوع سے نہ صرف سنی جائے گی بلکہ آپ کو انگریزی کا عالم بھی سمجھا جانے لگے گا۔طبقہ اشراف کا یہ لسانی شغف ہمارے قومی وقار کے ماتھے پر بدنما داغ بن چکا ہے۔
لباس کے معاملے میں ہماری غلامی کا سفر افلاک کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ قومی لباس سے حقارت آمیز برتائو اور مغربی آقائوں کے لباس کو باعث ِفخر ومباہات سمجھنے کا معاملہ ہماری قومی اقدار کا مستقل حصہ بن چکا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں قائد اعظم کے طرزِ عمل کی پیروی کا بھی ہرگز خیال نہیں ہے۔ قائد اعظم سے زیادہ فرنگی تہذیب کو قریب سے دیکھنے اور پھر اسے برتنے کا دعویٰ اور کسے ہو سکتا ہے۔لیکن برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آپ نے ۷۰برس تک استعمال کیا جانے والا فرنگی لباس ترک کر کے مستقل طور پر قومی لباس زیب تن فرمایا اور اس طرح تہذیبی طور پر اپنے 'آزاد' ہونے کا عملی ثبوت فراہم کیا۔ لیکن آج ہمیں اس طرح کے آزادی کے مظاہرے میں شخصی توہین اور وقار میں کمی دکھائی دیتی ہے۔
کچھ عرصہ پہلے لاہور کے ایک وکیل صاحب، جنہیں عدالت ِعالیہ میں مختلف اُمور کے متعلق رٹ پٹیشن داخل کرنے سے خاص شغف ہے، نے ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن دائر کی کہ عدالت ِعالیہ کے فاضل جج صاحبان کے لئے سیاہ شیروانی اور شلوار قمیص کی بجائے کوٹ پتلون، ٹائی کے علاوہ سر پر خاص برطانوی دور کا لباس پہننا ضروری قرار دیا جائے۔ کیونکہ اس طرح جج صاحبان زیادہ 'باوقار' نظر آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس صاحب کا اخباری بیان نگاہ سے گزرا جس میں انہوں نے اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کے لئے برطانوی دور کے لباس کے دوبارہ اِحیا کی ضرورت پر زور دیا تھا۔
میلسی ایک سول جج کے حوالے سے خبر نگاہ سے گذری جس میں انہوں نے ایک وکیل صاحب کو شلوار قمیص پر 'ٹائی' لگا کر حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ (۱۳؍فروری ۱۹۹۸ء )
بے حد تعجب کی بات ہے کہ جس لباس میں قائد اعظم کو کبھی الجھن محسوس نہ ہوئی، آج ہم اسے پہننے میں 'ہتک' محسوس کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی کاروائی کے دوران راقم الحروف کو قومی ومقامی لباس کی توہین کے دلخراش مناظر دیکھنے کو ملے۔ لودھراں سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی جو ہمیشہ چادر اور پگڑی پہن کر ایوان کی کاروائی میں حصہ لیتے، وہ جونہی ایوان میں داخل ہوتے تو ارکانِ اسمبلی اور گیلری میں بیٹھے صحافی اور سرکاری افسران ان کے لباس کے حوالے سے پھبتیاں کستے اور ان کے متعلق توہین آمیز جملے اُچھالتے، وہ ان کے ٹھٹھا مخول کا مرکز بنے رہتے۔ پنجاب اسمبلی کے اسی ایوان میں ۵۰برس تک نائب قاصد اور بیرے شیروانی اور لمبی پگڑی پہن کر 'ڈیوٹی' دیتے رہے ہیں۔ انگریزوں نے 'پنجاب کی پگڑی' کی توہین کرنے کے لئے اسے چھوٹے درجے کے ملازمین کے سروں پر رکھوا دیاتھا۔ سنا ہے حال ہی میں بعض اراکین کے احتجاج کے نتیجے میں اس قومی فرد گذاشت کی تلافی کر دی گئی ہے۔ کوٹ پتلون میں ملبوس ایک شخص کو دیکھتے ہی لوگ اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معزز شخص سمجھنے لگتے ہیں چاہے وہ جاہل مطلق اور عام درجے کا آدمی کیوں نہ ہو۔
ہمارے بچے ہمارے روشن مستقبل کے امین ہیں۔ قومی اقدار، قومی ثقافت اور قومی لباس سے محبت پیدا کرنے کی بجائے ہم ان کے اندر اپنے قومی ورثے کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے پبلک سکولوں میں بچوں پر پابندی ہے کہ وہ ہر صورت میں غیر ملکی 'یونیفارم' پہن کر آئیں۔ بچوں کے 'ریڈی میڈ' ملبوسات تیار کرنے والی فیکٹریاں صرف پتلون اور شرٹ بناتی ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو مقامی لباس میں دیکھنا پسند نہیں کرتیں۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پتلون شرٹ میں زیادہ 'سمارٹ' لگتے ہیں۔ شروع ہی سے قومی لباس کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے۔
قارئین کرام! یہ تو ہماری بدلتی ہوئی سماجی اقدار اور تہذیبی بیگانگی کے چند نمونے ہیں ورنہ تو ہماری ثقافت اور تہذیب ومعاشرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس طرح کی مثالیں تلاش نہ کی جاسکیں۔ ذرا غور فرمائیے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آخر ہم سیاسی آزادی مل جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو یورپ کی تہذیب کی اس مہمل تقلید کا مکلف کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تہذیبی تشخص سے محروم کرکے ہمیں 'کلون' بننے پریوں مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اپنا چہرہ ہی بیگانہ لگتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جس فکری وتہذیبی غلامی کا شکار ہیں، وہ بالآخر ہمیں سیاسی آزادی کے ثمرات سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گی۔وہ قوم جو انگریز کے سیاسی استعمار کے خلاف سینہ سپر ہوگئی تھی، آج مغرب کی ثقافتی آمریت اور تہذیبی تسلط کو خوش دلی سے کیونکر قبول کئے ہوئے ہے۔ یہ سوال غور طلب ہے!!
۱۱؍ستمبرکے بعد امریکہ اور یورپ سے پاکستانی خاندانوں کی اچھی خاصی تعداد 'وطن مالوف' کی طرف مراجعت پرمجبور ہوگئی ہے۔ یہ افرنگ زدہ گھرانے تہذیب کے 'وائرس' کو بھی ساتھ لے آئے ہیں جس سے لاہور جیسے شہر میں تمدنی نقالی کی وبا پھوٹنے کا خطرہ محسوس کیا جارہا ہے۔ ان خاندانوں کی صاحبزادیاں جو یورپ میں عادتاً جینز اور مغربی لباس میں ملبوس رہتی تھیں، پاکستان آنے کے بعداِسی لباس سے چمٹی ہوئی ہیں۔ لاہور کے جدید تعلیمی اداروں، پارکوں اور فیشن ایبل بازاروں میں ان افرنگ مآب صاحبزادیوں کی آزادانہ نقل و حرکت نے جدت پسند لاہوری خاندانوں کی لڑکیوں میں ثقاتی بیباکی کے رحجان کی مزید حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ گذشتہ ڈیڑھ سال کے دوران لاہور میں لڑکیوں میں جینز پہننے کا جنون وبا بن کر پھیلا ہے۔ ہماری طالبات اورجواں سال خواتین جینز پہننے کو فیشن اورجدیدیت کا سمبل سمجھنا شروع ہوگئی ہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ اچھے خاصے گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔
لاہور جیسے شہروں میں ثقافتی لبرل ازم کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فاسقانہ ارتباط کو فروغ دینے کے لئے شرمناک مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے تجارتی مفادات کے حصول کی خاطر لاہور کی معروف شاہراہوں پر نئے سٹائل کے ایسے ایسے اشتہارات(Bill Boards)کو متعارف کرایا ہے کہ جنہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ انسان لندن یا پیرس کی کسی شاہراہ سے گزر رہا ہے۔ ان اشتہارات میں لڑکے اور لڑکیوں کی باہمی قربتوں کے ایسے ایسے مناظر دکھائے جارہے ہیں جس کا ہماری ثقافت اور تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ گذشتہ دنوں میں اس کے خلاف ردّ عمل بھی سامنے آیا۔ بعض اشتہارات پر سیاہی پھینکنے کے واقعات بھی ہوئے۔ ہمارے لبرل دانشوروں نے اسے عورت کی توہین پر مبنی رویہ قرار دیا۔ ان اشتہارات میں عورت کے تقدس کی جس انداز میں تذلیل کی گئی تھی، اس کے خلاف وہ کبھی احتجاج نہیں کرتے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ذرائع ابلاغ کے بعد پاکستان کے بڑے شہروں کی شاہرات کو مغرب کے تہذیبی لبرل ازم کو فروغ دینے کے لئے استعمال کیا جارہا ہے۔
علامہ اقبال نے ۱۹۳۱ء میں خواجہ ناظم الدین تونسوی کو خط میں تحریر کیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ 'اسلام کے تحفظ کا مسئلہ' ہے۔ یہ مسئلہ آج زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے افغانستان اور عراق کو تاراج کرنے پر اکتفا ہی نہیں کیا، انہیں تہذیبی طور پر تباہ کرنے کی منصوبہ بندی بھی مکمل کرلی ہے۔ ڈیزی کٹر بموں سے تباہ شدہ یہ ممالک تہذیبی یلغار کا شکار ہیں۔ آج اسلام ہی نہیں ، اسلامی تہذیب اپنے وجود و بقا کی کشمکش سے دوچار ہے۔ افسوس آج ہم میں نہ کوئی اقبال ہے، نہ جمال الدین افغانی جو ہمیں ان خطرات کا احساس دلائے۔ ہمارا حکمران طبقہ حادثتاً مذہبی ہونے کے باوجود عملاً مغربی ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ آج بھی امریکی معاشرہ کی 'برتری'، وہاں کی 'آزادی' اور'نسل آدم کے وقار' کے ترانے ہمارے نوجوان نسل کے خام ذہنوں میں اُنڈیل رہے ہیں۔ یہ سب مظاہرے ہمارے اندر غلامی کے جذبات کی پختگی کی علامت ہیں۔ہم ثقافتی استعماریت کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔
ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور نوجوان امریکہ اور اس کے استعماری کلچر کے خلاف اس قدر بھی نفرت کے جذبات نہیں رکھتے، جتنا ہمارے ہاں کا مزدور طبقہ صنعت کار کے خلاف رکھتا ہے۔ ان کی نفرت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ اسلام پسند ہیں۔
۱۹۴۷ء میں ہم سیاسی طور پر آزاد ہوگئے تھے، مگر ہم نے مغرب کی فکری محکومی کو ترقی کا شاندار اُصول سمجھ کر گلے سے لگائے رکھا۔ آج ہم ایک دفعہ پھر 'سیاسی غلامی' کا طوق خوشی سے پہن چکے ہیں۔ فکری محکومی کا تسلسل بالآخر سیاسی غلامی پر منتج ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم سیاسی طور پر آزاد رہنے کے خواہش مند ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ذہنی غلامی کا طوق اُتار کر پھینکنا ہوگا۔ [محمد عطاء اللہ صدیقی]
بلاتبصرہ
''پسماندہ اسلام ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہے تو بسم اللہ۔ مجھے نہ کہو کہ میں داڑھی رکھوں، میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا۔ فلمی پوسٹر، میوزک، داڑھی نہ رکھنا، خواتین کا برقعہ نہ پہننا، شلوار قمیص، پینٹ اور ایل ایف او چھوٹے معاملات ہیں، انہیں ایشو نہ بنائیں۔ یہ چھوٹی سوچ اور چھوٹے ذہن کی بات ہے۔ پاکستان کو بڑے چیلنج درپیش ہیں!!
ایشو یہ ہے کہ ملک میں کون سا نظام ہونا چاہئے؟ ہمیں تہذیب یافتہ اور جدید اسلام چاہئے۔ پاکستانی معاشرے میں طالبان طرز کے اسلام کی کوئی جگہ نہیں۔ ایسے اسلام سے سارے منصوبے دھرے رہ جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ غیر اسلامی ملک ہے؟ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے مگر ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہئے جو معاشرے کو پسماندہ رکھے۔ ہم ترقی پسند اسلام کے حق میں ہیں۔ فیصلہ کریں طالبان والا اسلام چاہئے یا ترقی پسند؟ ہمیں عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دیا جارہا ہے۔ علما ہوش مندی سے کام لیں۔ قائداعظمؒ اور علامہ اقبالؒ کا تصور ترقی پسند پاکستان تھا، مذہبی ریاست نہیں۔ نفاذِ اسلام کے لئے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم برداشت والاکلچر چاہتی ہے۔ اسلام میں سب کے حقوق محفوظ ہیں۔ اس کی قدر کوسمجھیں۔'' (صدرپرویز مشرف کا خطاب از روزنامہ 'نوائے وقت' ۱۱؍ جون ۲۰۰۳ء)